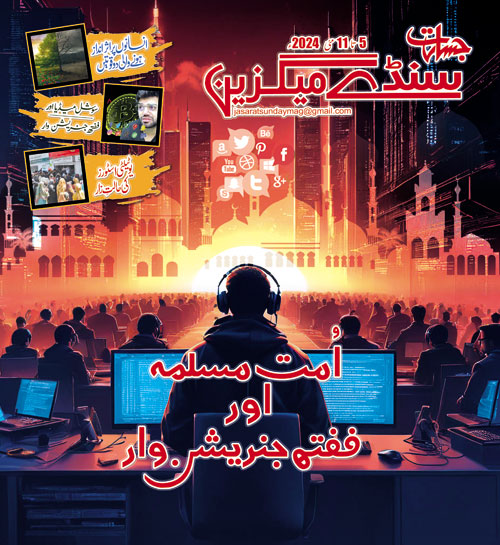(دوسری قسط)
۲۔ ماحول اور زبان و بیان کی صحت
سید مودویؒ کی پرورش انتہائی پاکیزہ علمی و مذہبی گھرانے میں ہوئی ان کے والد اور والدہ بچپن نے ہی سے ان کی تربیت و تعلیم کا خاص اہتمام کیا۔ عربی، فارسی اور دیگر علوم کے لیے اس کے مشہور اہل علم سے اکتساب کیا۔ مولانا دلّی کی وہ زبان بولتے اور لکھتے ہیں جو شرفا اور ادبا کی زبان تھی لاکھوں صفحات پر پھیلی ہوئی تحریروں میں شاید ہی زبان و بیان کی چند ہی غلطیاں نکالی جاسکیں۔
مولانا ماہر القادری کے نام ایک خط میں سید مودودیؒ لکھتے ہیں ’’اگرچہ مجھے زبان میں سند کا دعویٰ تو نہیں ہے لیکن اردو بولتے، لکھتے، سنتے اور پڑھتے ہوئے تقریباً پچاس برس گزر چکے ہیں۔ میں صحت زبان کے معاملے میں ہمیشہ متشدد رہا ہوں۔ زبان کی غلطی آپ میرے ہاں مشکل ہی سے پاسکتے ہیں۔ پچھلے پچاس سال کے اندر زبان کے تغیرات کے عکس آپ کو میری تحریرات میں ملیں گے۔ متروک الفاظ کا استعمال چھوڑتا چلاگیا ہوں اور نئے الفاظ استعمال کرتا رہا ہوں۔ اردو زبان و ادب پر گزشتہ ہر سال سے تقسیم ہند کی بدولت جو بحرانی کیفیت طاری ہوئی ہے میری انتہائی کوشش یہی ہے کہ زبان کو بگڑنے سے بچایا جائے اور صحیح معیار کو برقرار رکھا جائے۔
مصنف کے ذہن و کردار کی تعمیر اور افکار و نظریات کی تشکیل ایک مخصوص ماحول میں ہوتی ہے۔مصنف اپنے وقت کی سماجی اقدار اور ادبی مذاق سے آگاہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی ہر تخلیق زمانے کے مقتضیات سے ہم آہنگ ہوتی ہے چونکہ ادبی تخلیقات اپنے عہد اور ماحول کے سیاسی و سماجی شعور و آگہی کی نمائندگی کرتی ہیں، اس لیے مصنف کا اپنے ماحول سے متاثر ہونا ایک فطری عمل ہے۔ مولانا مودودیؒ کے اسلوب کی تشکیل میں ان کے پاکیزہ علمی و مذہبی گھرانے کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ انہوں نے بچپن ہی میں حالی کی شاعری اور آزاد کی انشا پردازی سے اکتسابِ فیض کیا تھا۔ ان کے والد محترم احمد حسن اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سنجیدہ علمی و مذہبی شعور رکھتے تھے۔ ان کی تربیت ہی کا اثر تھا کہ مولانا کی زبان میں پختگی شرافت، لطافت اور نفاست و شائستگی کی خصوصیات پیدا ہوئیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس دور کے مشہور اہل زبان اساتذہ کرام مولانا شریف اللہ خاں، مولانا اشفاق الرحمن کاندھلوی، مولانا عبدالسلام نیازی سے علوم عقلیہ و ادبیہ، حدیث و قرآن، فقہ، عربی ادب، فلسفہ، منطق اور علم الکلام کی تعلیم حاصل کی اور اسناد فراغت حاصل کیں بعد میں جوش ملیح آبادی، نیاز فتح پوری، مولانا محمد علی جوہر وغیرہ کی صحبت اٹھائی اور زندگی کا بیش قیمت زمانہ دہلی کے شرفاء کے ماحول میں گزارا تھا، اس لیے ان کی زبان دہلی کی ٹکسالی زبان ہے، جس میں سادگی و شگفتگی اور سلاست و روانی جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ محاورہ اور روزمرّہ پر ان کو پوری قدرت حاصل ہے۔ یہاں ان کی نثر دبستانِ دہلی کی نمائندہ نثر کہی جاسکتی ہے۔ وہ اپنی بات بڑے سلیقے سے ادا کرتے ہیں۔ ان کے فقرے چست اور ترکیبیں بڑی موزوں ہوتی ہیں، استعارہ کنایہ اور رمز سے وہ بھرپور کام لیتے ہیں۔
۳۔ موضوع کی جامعیت، اعتماد اور قطعیت
یعنی یہ کہ مصنف کس موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہے؟ اس کی نوعیت کیا ہے؟ اس کا موضوع ادب ہے یا سائنس، فلسفہ ہے یا تاریخ؟ مذہب ہے یا ساست؟ صحافت ہے یا افسانہ؟ ڈراما ہے یا انشائیہ؟ الغرض اصناف اور موضوعات کے بدلنے سے اسالیب میں بھی تبدیلی ہونا امرِ لازم ہے۔ وہ جس موضوع یا مسئلے کا ذکر کرتے ہیں اس کے تمام اجزاء اور تمام جہتیں موضوع کے لحاظ سے ایک خاص ترتیب کے ساتھ واضح کرتے ہیں اور پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کسی گوشے یا جزء کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ ان کی تحریروں میں وثوق اور اعتماد ہوتا ہے۔ وہ جو بات کہتے ہیں غور فکر کے بعد اعتماد اور یقین سے کہتے ہیں۔
مولانا مودودیؒ کی تحریروں کے موضوعات مختلف النوع ہیں۔ انہوں نے فلسفہ و سیاست، تاریخ و تمدن، معیشت و معاشرت، فکر و شخصیت، حدیث و سیرت، تفسیر قرآن اور مسائل حاضرہ پر خامہ فرسائی کی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کئی رسالوں اور اخباروں سے منسلک بھی رہے۔ ان کی تحریروں کے احاطے میں مختلف موضوعات تھے۔ چنانچہ اسلوب میں بھی تنوع فطری طور پر تھا۔ مولانا کی تحریروں میں اسلوب کا یہ تنوع بہت واضح اور نمایاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب ’’خطبات‘‘ اور رسالہ ’’دینیات‘‘ کا اسلوب تنقیحات و تفہیمات سے کافی مختلف ہے۔ اسی طرح تفہیم القرآن کا اندازِ بیان اسلامی تہذیب کے اصول و مبادی اور الجہاد فی الاسلام سے مختلف ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے موضوعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ موضوعات اور اسلوب میں تنوع اور رنگارنگی کے باوجود سادگی و صفائی اور شستہ انداز بیان ایک مشترکہ صفت کے طور پر ان کی تمام تحریروں میں نمایاں ہے۔
۴۔ حسنِ کلام، ندرتِ استدلال، فکر اور اسلوب کی ہم آہنگی
یہ امر بنیادی اہمیت رکھتا ہے کہ مولانا کا اسلوب تحریری نہیں بلکہ قرآن کی طرح تقریری ہے۔ وہ قاری سے مخاطب ہوکر گفتگو کرتے ہیں اور اس تخاطب میں ان کا لب و لہجہ مقرر کا لب و لہجہ ہوتا ہے مصنف کا نہیں بلکہ تفہیمی اور نرم ہوتا ہے۔ مولانا اپنی تحریروں کے پردے میں اپنے پڑھنے والوں سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کی ذہنی سطح سے بخوبی واقف ہیں اور چونکہ وہ مخاطب ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقت کی کمی کا احساس کرکے اختصار سے کام لیں۔ جن سے مخاطب ہیں ان سے قریب سے قریب تر ہوں۔ خود ان سے بالاتر نہیں بلکہ ان سے ہم سطح رہیں۔ ان کے کلام کی خوبی یہ ہے کہ مختصر اور جامع ہوتا ہے۔
مولانا کا انشاپردازانہ اسلوب اسلامی فکر اور اسلامی فکر کے جزئیات کو ساتھ لے کر آگے بڑھتا ہے۔ ان کے ہاں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ انہوں نے کسی دقیق مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے ادبی لطافتوں یا ادبی خوبیوں کی تخلیق میں متعلقہ مسئلے کے کسی پہلو سے روگردانی کی ہو۔ ان کا قلم قرطاس پر رواں دواں رہتا ہے۔ دلائل کی منطقیت یا قطعیت اور ادب کی چاشنی، دونوں چیزیں اس انداز سے ہم رنگ ہو جاتی ہیں کہ امتیاز کرنا ممکن نہیں ہوتا۔
علامہ اقبال پر جب تنقید کی جاتی ہے تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فلسفے کو اس مقام پر پہنچادیا ہے جہاں وہ شاعری بن گیا ہے۔ حکمت خون جگر کی آمیزش ہی سے شاعری بنتی ہے، خون جگر حکیمانہ تصورات میں شامل ہوکر شاعری کی وہ صورت اختیار کرلیتا ہے۔ یہ بات نثر نگار مولانا مودودیؒ کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ مولانا کی نثر ان کے افکار و تصورات کے بوجھ تلے دب نہیں جاتی بلکہ نکھر جاتی ہے۔ اس کی ادیبانہ شگفتگی ہر جگہ ہر مقام پر برقرار رہتی ہے۔
مولانا کا قلم فکر کے بڑے تنگ، ناہموار اور پتھریلے راستوں سے گزرتا ہے لیکن کیا مجال جو یہ قلم ادب کے معاملے میں کہیں عجز بیانی کا احساس دلائے اور یہ اس بنا پر کہ ان کی فکر اور ان کا اسلوب شروع سے لیکر آخر تک ہم آہنگ رہتے ہیں یہ ہم آہنگی وہی شخص قائم کرنے میں کامیاب ہوسکتا ہے جس کا قلم ایک عالم دین کا قلم بھی ہو اور ایک ادیب کا قلم بھی۔
۵۔ اسلوب کی مقصدیت
سید مودودیؒ نے زندگی ایک مشن کے تحت گزاری ہے۔ وہ زندگی کا ایک واضح اور متعین مقصد رکھتے ہیں۔ وہ بیسویں صدی میں اسلامی اصولوں کے تحت زندگی کی تعمیر نو چاہتے ہیں۔ ہر مصنف اور اس کی تخلیق کا مقصد مختلف ہوتا ہے۔ مولانا آزاد کے پیشِ نظر قارئین کو متاثر کرنا تھا، اس لیے ان کے یہاں تاثراتی اسلوب جلوہ فرما ہے۔ سرسید کا مقصد اصلاحِ ملت تھا، اس لیے انہوں نے مدلّل انداز بیان اختیار کیا جبکہ رشید احمد صدیقی، پنڈت رتن ناتھ سرشار اور پطرس بخاری وغیرہ نے قارئین کو محظوظ کرنے کی کوشش کی، اس لیے ان کے یہاں مزاحیہ اسلوب کار فرما ہے۔ اسلوب کے لیے مقصدیت بے حد اہم عنصر ہے۔ مقصد کے بدل جانے سے اسلوب بھی بدل جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال غالب کے خطوط اور ان کے تقریظوں کے اسلوب ہیں جو ایک دوسرے سے یک سر مختلف ہیں۔
مولانا مودودیؒ کی تصانیف کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بنیادی مقصد ایک ہے اور مختلف موضوعات کے مطابق ان کے مقاصد بھی مختلف تھے۔ ان تصانیف میں کہیں ان کا مقصد تہذیب و ثقافت پر تنقید ہے اور کہیں مسلمانوں کی اصلاح و بیداری، کہیں دینی و علمی مسائل کی توضیح و تشریح ہے اور کہیں قرآن و حدیث کی تفہیم و تفسیر۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی معرکہ آرا تصنیف ’’تفہیم القرآن‘‘ کا اسلوب ’’پردہ‘‘ سے مختلف ہے اور ’’خطبات‘‘ کا انداز بیان ’’تفہیمات‘‘ سے جدا ہے۔ موضوع کی تبدیلی نے ان کے اسلوبِ نگارش کو بھی متاثر کیا ہے۔ تفہیم القرآن، خطبات اور رسالہ دینیات وغیرہ میں آسان، عام فہم اور سادہ و دل نشیں لب و لہجہ اختیار کیا گیا ہے جبکہ تنقیحات، تفہیمات، پردہ اور اسلامی تہذیب کے اصول و مبادی وغیرہ کتابوں میں سنجیدہ و علمی اور متین و دبیز نثر کی خوبیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جس موضوع پر بھی سید مودودیؒ نے قلم اٹھایا ہے زندگی میں اقامت دین کا بنیادی مقصد کہیں نظر سے اوجھل نہیں ہوتا۔ ان کی تحریروں میں ماضی کے دور کا احساس نہیں ہوتا بلکہ مستقبل کی صورت گری کا جذبہ ابھرتا ہے۔ ایک اعلیٰ نصب العین اور ایک بہتر زندگی کی تعمیر کا احساس جاں گزیں ہوتا ہے۔
۶۔ مخاطب کے ذہنی اور علمی معیار کے نبض شناس
مخاطب کے ذہنی معیار اور علمی استعداد کے پیش نظر ہی مصنف کوئی اسلوب اختیار کرتا ہے۔ مصنف نبض شناس بھی ہوتا ہے اور مخاطب کی نفسیات سے پوری طرح آگاہ بھی، اس لیے اسے یہ بھی پیش نظر رکھنا پڑتا ہے کہ مخاطب کس سماجی طبقے سے تعلق رکھتا ہے؟ اس کے انفرادی و اجتماعی مسائل کیا ہے؟ مصنف وہی اسلوب اختیار کرتا ہے جو مخاطب کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوسکے۔ مصنف اگر ان باتوںکا خیال نہ رکھے گا تو اس کی تحریروں تک مخاطب کی ذہنی رسائی نہ ہوسکے گی اور وہ اپنے مقصد، فن اور ابلاغ میں ناکام و نامراد ہوگا۔
مولانا مودودیؒ کے مخاطب سماج کے ہر طبقے اور ہر معیار کے لوگ رہے ہیں۔ ان کے مخاطب کبھی علمائے کرام، کبھی ارباب حکومت، کبھی مشاہیر وقت، کبھی گائوں دیہات کے سادہ لوح انسان اور کبھی جویائے علم و تحقیق بھی رہے ہیں۔ مولانا مودودیؒ کو اپنے مخاطب کے ذہنی معیار، علمی استعداد اور نفسیات و ذوقیات کا گہرا شعور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ عام خواندہ طبقے سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کا اندازِ بیان سادہ اور عام فہم ہوجاتا ہے، جب وہ طبقۂ اعلیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں تو حکیمانہ نکتہ آرائی اور عالمانہ بصیرت افروزی سے کام لیتے ہیں۔
مولانا مودودیؒ کی ہمہ جہت شخصیت کو علمی و مذہبی اور سنجیدہ ماحول، موضوعات کی رنگارنگی، مقصد کی جہت اور مخاطب کی صلاحیت جیسے عناصر کی منضبط اور مربوط ترتیب و تنظیم نے ایک باوقار اسلوب عطا کیا ہے۔ اس اسلوب میں کون کون سی خوبیاں تھیں اور اس نے ترسیل و ابلاغ کی ذمہ داری کہاں تک ادا کی، اس کا تجزیہ کرنے سے قبل اردو کے نثری اسالیب کا بھرپور جائزہ لینا ضروری ہے جس کے پسِ منظر میں مولانا مودودیؒ نے لکھنا شروع کیا۔
۷۔ ابہام سے پاک واضح تحریر
مولانا کا زندگی کا مقصد واضح اور متعین ہونے کی وجہ سے ان کی تحریر میںا عتماد پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی تحریر ابہام سے پاک ہوتی ہے۔ ان کی تحریر میں حشو و زوائد کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ ایجاد و اطناب بطور صنعت تو موجود ہیں لیکن الفاظ، معانی میں بڑا حسین ربط و تعلق قائم ہے۔ نہ الفاظ اتنے زیادہ کہ داستان طرازی معلوم ہو اور نہ اتنے کم کہ متن کا مفہوم بھی واضح نہ ہو۔ الفاظ کے انتخاب، جملوں کی تراکیب، عبارت کی بندش، تماثیل اور مثالوں کا برجستہ استعمال، پیرا گراف اور مضمون کی ترتیب مجموعی طور پر ان کی ہر تحریر کو واضح اور محکم بناتے ہیں۔ ان کی کوئی تحریر مبہم اور غیرواضح نہیں ہوتی۔ ان کے الفاظ ان کے خیالات کے ابلاغ کا ذریعہ بنتے ہیں۔
مولانا مودودیؒ کے معاصرین
مولانا مودودیؒ کی نثر اردو ادب میں مذہبی نثر کا کمال ہے۔ ہمارے مترجمین، مبلغین، مصلحین اور مفکرین اردو نثر کو عرصے سے اپنے لیے آلہ کار بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن شریف کے ہزاروں تراجم کی نثر کا ایک الگ دائرہ ہے۔ مسائل پر بحثوں اور مسائل کی وضاحت پر سینکڑوں چھوٹی بڑی کتابیں نظر آتی ہیں جو اپنی الگ نثر رکھتی ہیں مگر مولانا مودودیؒ کی نثر کے مقابلے میں ان سب اقسام کی مذہبی نثر وہی مقام رکھتی ہے جیسی کہ مرثیوں کی اردو نظم میرانیس سے پہلے رکھتی تھی۔ مولانا مودودیؒ کے معاصرین میں جنہیں امتیازی حیثیت رہی، ان میں خواجہ حسن نظامی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبدالماجد دریابادی اور ابوالحسن علی ندوی کے نام اہم ہیں۔ موضوع و مواد اور دائرہ کار کے اعتبار سے ان کے یہاں کئی خوبیاں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں مگر فکر و نظر کے اظہار و بیان کے لیے ان لوگوں نے جو جو اسلوب اختیار کیے وہ باہم مختلف ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کی تحریر میں دل کشی، بے تکلفی اور بے ساختگی کے ساتھ رجائیت، قنوطیت اور سوز و گداز بھی ہے جبکہ مولانا آزاد کا شہرہ ان کے عرفان ادب، بلند آہنگ نثر اور فلسفیانہ و مفکرانہ انداز بیان سے ہے۔ مولانا عبدالماجد دریابادی کے یہاں دہلوی اور لکھنوی نثر کی خوبیاں ہم آمیز ہوکر ایک خوب صورت مرقع پیش کرتی ہیں اور مولانا علی میاں کی طرزِ نگارش پر تاریخ و تصوف اور احیائے دین چھایا ہوا ہے۔ اس لیے ان کی زبان میں پختگی اور سنجیدگی کے ساتھ خوب صورت دردمندی بھی ہے۔
(جاری ہے)