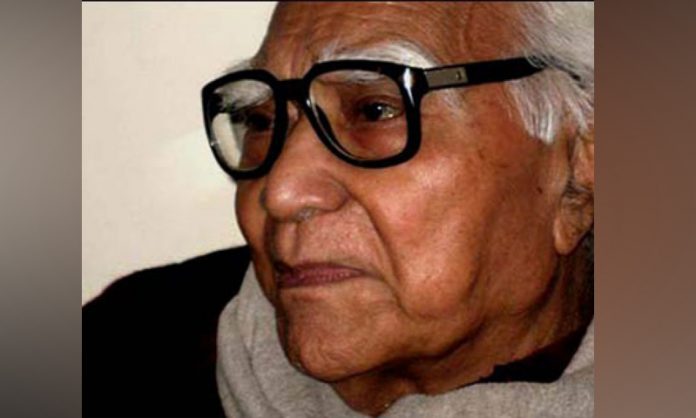شوکت صدیقی: ناول لکھنے کے لیے جو منصوبہ بندی عموماً کی جاتی ہے اور کرداروں کو کاٹ چھانٹ کر واقعات کی ترتیب و تشکیل سے کہانی کو جس طرح اجاگر کیا جاتا ہے‘ میں نے یہ سارا اہتمام ’’خدا کی بستی‘‘ میں نہیں کیا۔ میں حافظ قرآن ہوں‘ میرا حافظہ الحمدللہ بہت اچھا ہے اور اس سے مجھے خاصی مدد ملتی ہے۔ اس لیے مجھے نوٹس لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس زمانے میں‘ میں ’’ٹائمز آف کراچی‘‘ میں ملازم تھا۔ شام چھ بجے دفتر پہنچتا اور صبح چار بجے لوٹتا تھا۔ بڑا پُرآشوب دور تھا۔ دفتر سے واپسی پر تھوڑی دیر آرام کرتا اور پھر جو لکھنے بیٹھتا تو ایک بجے دن تک لکھتا رہتا۔ عجیب دیوانگی کا عالم تھا۔ کہانی کا خاکہ میرے ذہن میں موجود تھا۔ میں اس کے مطابق کہانی کو پھیلاتا اور آگے بڑھاتا جارہا تھا۔ ذہن اتنا حاضر تھا کہ مجھے یاد رہتا تھا کہ میں کہاں تک لکھ چکا ہوں اور مجھے کہانی کو آگے کہاں تک لے جانا ہے۔ میرے اندر ایک لاوا تھا جو ابلنے کے لیے بے تاب و بے قرار تھا۔ مجھے لکھنے کے لیے اپنے اندر تحریک پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی‘ قلم اٹھایا اور لکھنے بیٹھ گیا۔ وہ 1957ء کا زمانہ تھا‘ آج 1984ء ہے۔ ان دوزمانوں میں بڑا فرق ہے۔
طاہر مسعود: ’’خدا کی بستی‘‘ کا کتنا حصہ حقائق پر مبنی ہے؟
شوکت صدیقی: اس وقت میں آپ سے اپنے ائر کنڈیشنڈ کمرے میں بیٹھا گفتگو کر رہا ہوں‘ لیکن 1950ء میں اپنا افسانہ ’’تیسرا آدمی‘‘ لکھتے وقت میں معاشی اعتبار سے ایک تباہ حال ادیب تھا۔ اس زمانے میں ادیب پیسے لے کر کھا جاتے تھے اس لیے ابن انشا کو ضمانتی مقرر کیا گیا تھچ اکہ جب میں اپنا مسودہ انہیں دو تو وہ اس کا معاوضہ پچاس روپے مجھے اد اکریں گے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جیکب لائن کے ایک تنگ کوارٹر میں رات گئے میں بیٹھا کہانی لکھ رہا تھا اور وہاں بیٹھے بدقماش لوگ جوا کھیل رہے تھے‘ جوئے کی ایک کھردری قسم ہوتی ہے جسے ’’مانگ پتہ‘‘ کہتے ہیں۔ وہ مانگ پتہ کھیل رہے تھے اور چرس پی رہے تھے۔ کمرہ دھویں سے بھرا ہوا تھا اور میں چارپائی پر تکیے سے ٹیک لگائے کہانی لکھنے میں مگن تھا۔ وہ کھیلتے کھیلتے مجھے مخاطب کرکے کہتے ’’شوکت صاحب! معسوکوں کو خط لکھے جارہے ہیں۔‘‘ ’’خدا کی بستی‘‘ کی کہانی اسی زمانے کی ہے تاہم میں اصرار کے ساتھ کہوں گا کہ اس کے کردار میرے جانے پہچانے نہیں ہیں۔ یعنی وہ ایسے نہیں ہیں کہ زندگی میں وجود رکھتے ہوں۔ اس کے برعکس ’’جانگلوس‘‘ اور کسی حد تک ’’چہار دیوار‘‘ کے کرداروںکا وجود حقیقی ہے اور اس میں بیشتر واقعات بڑی حد تک حقائق پر مبنی ہیں۔
طاہر مسعود: ’’خدا کی بستی‘‘ کے بعض کرداروں کے بارے میں آپ کے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ وہ جیتے جاگتے کردار ہیں اور آپ انہین اچھی طرح سے جانتے ہیں خصوصاً سلطانہ اور ڈاکٹر موٹو کے کردار کو۔
شوکت صدیقی: میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے‘ نہ میں ایسے کسی ڈاکٹر کو جانتا ہوں اور نہ سلطانہ جیسی کسی لڑکی کو۔ قصہ یہ تھا کہ میں نے ایک کہانی بچوں کے بارے میں لکھی تھی‘ ان بچوں کے بارے میں جو بچپن ہی میں جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی میں نے چھپنی کے لیے ’’لیل و نہار‘‘ مین دی۔ اس کی ایڈیٹر سبط حسن صاحب کہنے لگے کہ یہ کہانی اس بات کی متقاضی ہے کہ میں اس موضوع پر مزید لکھوں۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ’’خدا کی بستی‘‘ بنیادی طور پر جرائم پیشہ بچوں کی کہانی ہے۔ باقی سارے کردار خواہ وہ ڈاکٹر کا ہو‘ سلطانہ کا یا اس کی ماں کا‘ یہ سب معاون کردار ہیں۔ راجا یا نوشہ بہتر انسان بننے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں لیکن معاشرہ یا ماحول انہیں نیکی کی راہ پر چلنے نہیں دیتا۔
طاہر مسعود: آپ کے پاس ناول میں جرائم پیشہ طبقے کی عکاسی جس عمدگی سے کی گئی ہے اس کی مثال اردو کے کسی اور ناول میں نہیں ملتی۔ اس کے لیے آپ نے یقینا جرائم پیشہ طبقے کا خصوصی طور پر مشاہدہ کیا ہوگا؟
شوکت صدیقی: میرا تعلق اگر جرائم پیشہ طبقے سے نہیں رہا تو میں نے کم از کم ان کا مشاہدہ ضرور کیا ہے۔ ہندوستان سے یہاں آنے کے بعد مجھے رہائش کا مسئلہ درپیش ہوا‘ جہاں بھی سر چھپانے کی جگہ ملی وہیں ٹھہر گیا۔ رہائش کے سلسلے میں مجھے ان جرائم پیشہ لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ان کی گفتگو سنی‘ ان کے حوالے سے لوگوں نے واقعات بتائے۔ ’’خدا کی بستی‘‘ میں بردہ فروش‘ شاہ جی‘ خلیفہ گرہ کٹ اور ان جیسے دوسرے کردار یقینا حقائق پر مبنی ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے‘ ان سے ملا ہوں‘ ان کے متعلق میری معلومات بہت اچھی ہیں۔ میں نے سال ڈیڑھ سال ان کے درمیان گزارا ہے۔ میں دفتر سے رات گئے لوٹتا تھا تو یہ لوگ اڈہ جمائے بیٹھے رہتے تھے۔
طاہر مسعود: خدا کی بستی لکھتے وقت آپ کو اندازہ تھا کہ یہ ناول اتنی مقبولیت حاصل کرے گا؟
شوکت صدیقی: میں نے ’’خدا کی بستی‘‘ کو مکمل کیا اور ایک عجیب سی سرشاری کی کیفیت میں کافی ہائوس پہنچا۔ وہاں مظفر علی سید مل گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ’’میں نے ایک ناول لکھا ہے۔‘‘
انہوں نے پوچھا ’’کیا اسے مکمل کر لیا ہے؟‘‘
کہاں ’’ہاں! مکمل کر لیا ہے‘ یہ ایک طویل ناول ہے۔‘‘
پوچھنے لگے ’’تمہارا کیا خیال ہے؟‘‘
میں نے جواب دیا ’’میں یہ تو نہیں کہتا کہ ٹالسٹائی کے اینا کرینینا جیسا بڑا ناول ہے لیکن میں نے اپنے طور پر اسے نہایت اطمینان سے لکھا ہے اور یہ چھوٹا ناول بہرحال نہیں ہے۔‘‘
بولے ’’اچھا! مجھے ذرا مسودہ دینا‘ میں دیکھوں گا۔‘‘
میں نے پہلے مسودہ دینے سے انکار کیا لیکن پھر اصرار پر ان کے حوالے کر دیا‘ وہ اسے پڑھ کر واپس کرنے آئے تو میں نے پوچھا کہ ’’تم نے اسے کیسا پایا؟‘‘ بولے ہاں تم نے ناول تو لکھا ہے‘ کیا تم اسے چھپوا رہے ہو؟‘‘
مجھے ان کے رویے سے سخت مایوسی ہوئی لیکن مجھے یقین تھا کہ یہ ناول بڑا ناول ہوگا۔
طاہر مسعود: کیا یہ ناول شائع ہوتے ہی مقبول ہو گیا تھا یا اسے دھیرے دھیرے مقبولیت حاصل ہوئی؟
شوکت صدیقی: ناول شائع ہوتے ہی مقبول ہو گیا تھا۔ اس کا پہلا ایڈیشن تو نہایت تیزی سے فروخت ہوا اور 1960ء میں جب اسے آدم جی پرائز ملا تو پبلشر کے دل میں بے ایمانی پیدا ہوئی۔ میں نے اسے صرف دو ایڈیشن دیے تھے لیکن جب اس نے دیکھا کہ ناول بہت بک رہا ہے تو اس نے اس کی فوٹو فلم بنا لی اور اسے شائع کرنا شروع کردیا اس ناول کو عوامی سطح پر اس وقت بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی جب ٹی وی پر اس کی ڈرامائی تشکیل ہوئی۔ اس زمانے میں کسی گلی سے گزرتا تو لوگ ایک دوسرے کو بتاتے تھے ’’وہ دیکھو خدا کی بستی کے مصنف جارہے ہیں۔‘‘ دکان دار خود ہی رعایت دے دیتے تھے۔ اس ناول نے مجھے وہ شہرت دی جو عموماً شو بزنس کے افراد کو ہی ملتی ہے۔
طاہر مسعود: ’’خدا کی بستی‘‘ کی کہانی دو متوازی خطوط پر سفر کرتی ہے۔ ناول کو ایک پہلو سے دیکھیے تو معاشرذے کے تاریک حقائق ابھر کر سامنے آتے ہیں اور صورت حال سے امید کی ایک کرن پھوٹتی ہے۔ یہ اسکائی لارک ہیں جو معاشرے میں تعلیم عام کرکے اسے بدلنا چاہتے ہیں۔ ناول کے اس دوسرے پہلو نے سماجی حقیقت نگاری کے نقطہ نظر سے آپ کے ناول کو کم زور نہیں بنا دیا؟
شوکت صدیقی: یہ عجیب اتفاق ہے کہ قارئین اور ناقدین ناول کے جس حصے کو حقائق قرار دیتے ہیں‘ دوسرا سر تخیل کی پیداوار ہیں اور جنہیں وہ آئیڈیل یا تخلیقی کردار کہتے ہیں‘ وہ سب کے سب مبنی بر حقیقت ہیں۔ ناول کے اسکائی لارک کا تعلق حقیقت سے ہے۔ ایکی زمانے میں اردو کے مشہور افسانہ نگار حیات اللہ انصاری نے تحریک تعلیم بالغاں شروع کی تھی‘ ان کی تحریک میں شامل افراد خیالات کے اعتبار سے قوم پرست تھے میں ان نوجوانوں میں شامل تھا۔ انصاری صاحب نے پس ماندہ علااوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف مراکز قائم کیے تھے۔ ان بستیوں میں جا کر ہم لوگوں کو تعلیم دیتے اور ہفتے اپنے مرکز کی رپورٹ اجتماعی میٹنگ میں پیش کرتے۔ انصاری صاحب انچارج کی حیثیت سے ہمارے کام کا جائزہ لینے کے لیے عین اس وقت جب ہم لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے تھے‘ موقع پر پہنچ جاتے اور خاموشی سے پیچھے کھڑے رہتے۔ یہ سب کچھ بالکل اسی طرح تھا جیسا میں نے ناول میں پیش کیا ہے۔ ہم نے پیٹرومیکس‘ لالٹین‘ بورڈ‘ چاک وغیرہ کا انتظام کیا ہوا تھا اور طریقہ تعلیم یہ تھا کہ اَن پڑھ باشندوں کو حروف تہجی کے بجائے صوتی اعتبار سے لفظوں کی شکلوںسے آگاہ کرایا جائے۔ جب ہم نے تعلیم دینا شروع کیا تو مسائل ابھر ابچھر کر سامنے آئے مثلاً کوئی شاگرد بیمار پڑآ تو بستی میں اس کے علاج معالجے کی سہولت نہیں ہے‘ کوئی بے روزگار ہے تو اس کی نوکری کا بندوبست نہیں ہورہا ہے۔ کسی علاقے میں ملیریا پھیل گیا ہے تو لوگ سینٹر بند کر دینا چاہتے ہیں کہ کہیں بیماری پھیل نہ جائے۔ تب ہم نے اپنے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ ان بستیوں میں اسپتال اور دارالمطالعے بھی قائم کیے جائیں۔ ان دنوں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس تحریک کے پیچھے کمیونسٹ پارٹی کا ہاتھ ہے۔ یہ تاثر بالکل غلط تھا اس لیے کہ کمیونسٹ تحریک انقلابی تحریک پر یقین رکھتی ہے۔ ہماری تحریک تو نچلے متوسط طبقے کی اصلاحی تحریک تھی جسے میں نے اپنے ناول کا موضظع بنایا۔
طاہر مسعود: آپ کے ناول کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ بدی کی قوتیں نیکی‘ حسن اور صداقت کی اقدار پر غالب آتی جارہی ہیں جس کے نتیجے میں ناول کا قاری حزن‘ مایوسی اور قنوطیت کا شکار ہو جاتا ہے‘ کیا یہ تاثر درست ہے؟
شوکت صدیقی: یہ مسئلہ اس وقت میرے سامنے شدت سے اٹھا جب اس ناول کو ٹیلی ویژن پر پیش کیا گیا۔ ٹی وی کے اربابِ اقتدار نے تو اس سلسلے میں مجھ پر کوئی دبائو نہیں ڈالا لیکن ناظرین کی جانب سے خطوط اور ٹیلی فون کا تانتا بندھ گیا۔ مطالبہ تھا کہ سلطانہ کی ماں کو نہ مارا جائے اور فرزند علی کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ میں نے کہا کہ ہمارا مزاج میلوڈراما کا مزاج ہے۔ ڈرامے کی بنیاد تضاد پر قائم ہے اور ناول کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے۔ میلو ڈرامے کا اختتام عموماً خوش کن ہوتا ہے‘ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ مجرم اور ظالم لوگ ہمیشہ اس دنیا میں سزا نہیں پاتے اور نہ ہی ان کا انجام درد ناک ہوتا ہے۔ ظالم ظلم کرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ حقیقت نگاری کا تقاضا تھا کہ معاشرے میں جو کچھ اور جس طرح ہو رہا ہے‘ میں اسے ویسے ہی بیان کروں۔ آپ نے دیکھا کہ ناول میں صداقت کی قوتیں حاوی نہیں ہوئیں۔ طاقت ور قوتیں وہی ٹھہریں جو بدی کی قوتیں تھیں۔ خان بہادر فرزند علی پر ترقی اور خوش حالی کے دروازے کھلتے چلے گئے اور پس ماندہ مظلوم لوگ جدوجہد کے باوجود مواقع حاصل نہ ہونے پر تباہ ہو گئے۔ یہ معروضی حقیقتیں ہیں جن کو میں نظر انداز نہیں کرسکتا۔ معروضی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دن ہے تو دن ہے‘ ہم اسیض اپنی خواہشات سے نہیں بدل سکتے۔ میں نے خواہشات کے بجائے حقائق کا اظہار کیا ہے۔
طاہر مسعود: نظریاتی اعتبار سے آپ بائیں بازو کے گروپ سے وابستہ ادیب تصور کیے جاتے ہیں‘ آپ کے بارے میں اب کہا جاتا ہے کہ آپ نے بحیثیت ادیب نظریاتی کردار ادا کرنا ترک کر دیا ہے‘ کیا یہ گمان درست ہے؟
شوکت صدیقی: انفرادی نقطۂ نظر جامد نہیں ہوتا۔ کوئی نصب العین جسے آپ نے ایک مرتبہ وضع کر لیا ہو‘ ناقابل تغیر نہیں ہوتا۔ تبدیل ہوتے ہوئے معروضی حالات فرد کے خیالات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ خیالات کی تبدیلی کا عمل ارتقائی عمل ہے۔ میرے نظریات میں بھی تبدیلی پیدا ہوئی ہے‘ مجھے اس سے انکار نہیں۔ پہلے میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے ساتھ تھا اب میں ایک گوشہ نشین آدمی ہوں‘ میرا کوئی گروہ نہیں ہے‘ کوئی حلقہ نہیں ہے۔
طاہر مسعود: آپ کے نظریات میں جو تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں‘ ان کی نوعیت کیا ہے؟ کیا
آپ اس کی وضاحت کرنا پسند کریں گے؟
شوکت صدیقی: چالیس سال کے عرصے میں معاشرے میں کئی بنیادی نوعیت کے تغیرات رونما ہوئے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی۔ نئی ایجادات ہوئیں‘ ہماری زندگی میں کمپیوٹر داخل ہو گیا۔ ماضی میں میری سوچ تھی کہ معاشرے کی تشکیل اس طرح ہونی چاہیے کہ خیر کی قوتوں کو تقویت ملے‘ زندگی مزید دل کش ہو جائے‘ لیکن آج کے حالات نے ان خوابوں کو ملیامیٹ کر دیا ہے۔ میں اشتراکی انقلاب کا اب بھی قائل ہوں‘ لیکین اب میں ہر اس اشتراکی انقلاب کا مخالف ہوں جو روس یا چین کے حوالے سے آئے۔ اب میں اسی انقلاب‘ اسی نظریۂ حیات کو پسند کروں گا جو ہمارے ملک کے معروضی حالات کے لیے سازگار ہو۔ عقیدہ پرستی سے دامن چھڑا کر پہلے تو ہمیں اس سوال پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے عوام سوشلسٹ انقلاب چاہتے ہیں یا نہیں اگر نہیں چاہتے تو ہم انقلاب کس طرح لا سکتے ہیں۔ انقلاب اوپر سے تو مسلط نہیں کیا جاسکتا۔ اختتام