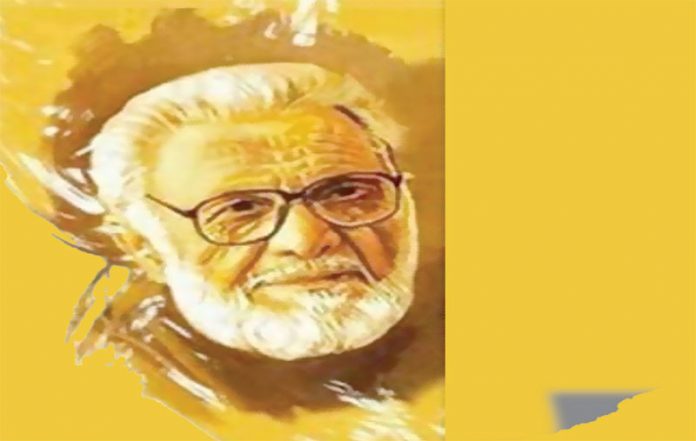کرداروں میں اس وقت زندگی پیدا ہوتی ہے جب ادیب اسے اپنا فلسفہ دینا چاہتا ہے
کرداروں میں اس و قت زندگی پیدا ہوتی ہے جب ادیب اسے اپنا فلسفہ دینا چاہتاہے
آدی دیکھتے ہی دیکھتے کیسے‘ کیوں کر بدل جاتا ہے؟ کون بدل دیتا ہے؟ مذہبی سے غیر مذہبی اور غیر مذہبی سے انتہائی مذہبی۔ یہ اندر کی تبدیلی‘ زاویۂ نظر کا بدل جانا‘ زندگی اور معاملات زندگی کو ایک خاص طریقے سے دیکھتے‘ سمجھتے اور محسوس کرتے بالکل ہی الگ اور مختلف زاویے سے دیکھنے لگ جانا اور اس کے زیر اثر لباس‘ چہرے مہرے‘ عادات و اطوار‘ طرز کلام سب میں یکسر تغیر کا آجانا کیا اسے ہم فکر کے ارتقا‘ مطالعے مشاہدے کا نتیجہ کہیں گے؟ ان سوالوں کا الجھنوں کا کبھی کوئی واضح اطمینان بخش جواب دینا شاید ہی کسی کے لیے ممکن اور آسان ہو۔
جب ہم نے اپنی طالب علمی کے زما ے میں اشفاق احمد کو پڑھنا شروع کیا تو ’’ایک محبت سو افسانے‘‘ تک پوری اور بُری طرح ان کے افسانوی سحر میں گرفتار ہو چکے تھے۔ پھر اشفاق احمد نے اپنا رُخ میڈیا کی طرف کر لیا‘ چھپے ہوئے لفظ سے ان کا رشتہ ناتا کمزور پڑتا گیا۔ لیکن میڈیا کی طرف جا کر وہاں بھی ان کی تخلیقی صلاحیت اپنے جوبن پر ہی رہی اور انہوں نے سیاہ و سفید ٹیلی ویژن پر ’’ایک محبت سو افسانے‘‘ کے عنوان سے اپنے ڈراموں میں محبت کے متنوع رنگ دکھائے تو یہاں بھی ان کی انفرادیت‘ ڈرامے کے فن پر ان کی مضبوط گرفت اور کردار و مکالمہ نگاری میں مہارت کا لوہا مان لیا گیا۔ ریڈیو پر تلقین شاہ اور ٹیلی ویژن پر ان کے ڈراموں نے ان کے متاثرین اور مداحوں کے حلقے کا دائرہ پورے ملک میں وسیع کردیا۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا جب رومانی افسانے اور ڈرامے لکھنے والے اشفاق احمد کے اندر ایک مصلح‘مبلغ‘ ایک ریفارمر نے آنکھ کھولی جس نے بتدریج ان کی شخصیت‘ اندازِ فکر اور اظہار خیال کا پوری طرح احاطہ کرلیا۔ ’’توتا کہانی‘‘ اور ’’ڈرامے‘‘ سے ٹی وی کے پروگرام ’’زاویہ‘‘ تک ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد‘ ایک مشن ساری کلامی اور تحریری سرگرمیوں کا محور و مرکز بنتا گیا۔ آدمی کی اخلاقی اور قلبی حالت کو بدلنا۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی داڑھی بھی سج گئی۔ نئی نسل‘ نوجوان نسل کے درمیان بیٹھ کر ان کے ذہن کے جالوں کو ان کے استفسارات کے اچھے‘ متاثر کن جواب دے کر صاف کرنا‘ انہیں بھلی باتیں بنانا اور اپنے تجربات اور واقعات کچھ ’’بابے‘‘ کے ملفوظات‘‘ کچھ مطالعے کا نچوڑ… اب کسے یاد کہ یہ وہی اشفاق احمد تھے جنہوں نے اردو ادب کو ’’گڈریا‘‘ جیسا بے مثال افسانہ دیا۔
اب تو کتابوں کی دکانوں پر ’’زاویہ‘‘ حصہ اوّل، دوم، سوم، چہارم کی جلدیں بکتی ہیں۔ ایڈیشن پر ایڈیشن چھپتے اور ہاتھوں ہاتھ نکل جاتے ہیں۔
رومانی افسانہ نگارکھو گیا اور اخلاق کا سبق پڑھانے والا اشفاق احمد آج بھی ’’زاویہ‘‘ کے نسخے واٹس اپ اور نیٹ پر اس کی ’’ٹیلی ویژن ٹاک‘‘ اسی طرح مقبول ہیں جیسے کسی صوفی اور ولی اللہ کے ملفوظات پر مبنی مقدس کتابیں‘ جیسے فواید الفواد۔
زیر نظر کتاب کے لیے میں اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کا انٹریو کرنے بہ طور خاص لاہور گیا تھا۔ ان دنوں وہ اردو سائنس بورڈ کے ڈائریکٹر تھے۔ میں نے دفتر میں انہیں بہت مصروف مگر بے حد چاق و چوبند پایا۔ ایک ادارے کے منتظم کی حیثیت میں ان کی بہترین انتظامی صلاحیت و اہلیت کا مشاہد بھی ہوا۔ جب گفتگو کے خاتمے پر میں نے ان سے بانو قدسیہ صاحبہ سے انٹرویو کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے فون کرکے انٹرویو کا اہتمام کیا‘ ساتھ ہی اپنے گھر ’’داستانِ سرائے‘‘ جانے کے لیے دفتر کی گاڑی بھی فراہم کر دی۔ ان سے میری ذاتی قربت تو نہ رہی لیکن ایک دن ان کے ڈراموں کی کتاب ’’ایک محبت سو ڈرامے‘‘ میں ان کا دل کو چھو جانے والا ڈراما ’’قرۃ العین‘‘ پڑھتے ہوئے محض دو ایک فقروں میں اس اشفاق احمد کو میں نے دریافت کر لیا جو آہستہ آہستہ زمین سے اٹھتا گیا اور پھر اس کا سمبندھ اوپر آسمان سے ہو گیا۔
آدمی بھی زندگی ہی کی طرح بھید ہے۔
اس بھید کو سمجھنے کی فکر کسے ہو۔ جو سوچا تھا گہرائی میں اتر کے وہ بھی تو اشفاق احمد ہی تھا جو نہ رہا۔
اشفاق احمد 22 اگست 1927ء کو پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے اردو میں ایم اے کی سند لی۔ اٹلی اور فرانس کی جامعات سے اطالوی اور فرانسیسی زبانوں میں ڈپلومہ کیا۔ نیویارک‘ امریکا سے ریڈیائی نشریات کی تربیت حاصل کی۔ درس و تدریس سے ابتدا میں وابستہ رہے۔ دیال سنگھ کالج لاہور اور روم یونیورسٹی میں پنجابی زبان بھی پڑھائی‘ پھر صحافت کا پیشہ اختیار کیا۔ ہفت روزہ ’’لیل و نہار‘‘ میں مدیر کا فریضہ انجام دیا۔ پھر اپنا رسالہ ماہنامہ ’’داستان گو‘‘ نکالا جو تین سال تک جاری رہا۔ سرکاری ملازمت کا بھی تجربہ کیا۔ چار سال تک ڈائریکٹر آر سی ڈی ریجنل‘ کلچرل انسٹی ٹیوٹ (پاکستان برانچ) اور پھر ڈائریکٹر وفاقی اردو سائنس بورڈ بھی رہے۔ ان کی ادبی خدمات پر 1979ء میں حکومت نے ادب کے شعبے میں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا۔ 7 ستمبر 2004ء کو دنیائے فانی سے رخصت ہوئے۔
تصانیف:۔
افسانے:۔
-1ایک محبت سو افسانے (1951ء)۔
-2 اجلے پھول (1953ء)۔
-3 سفر مینا (1938ء) اس مجموعے میں ناولٹ ’’مہمان بہار‘‘ بھی شامل ہے۔
سفر نامہ: ’’سفر در سفر۔‘‘
ترجمہ: ’’وداع جنگ‘‘ (ہیمنگولے کا ناول اے فیئر ویل ٹو آرمز کا ترجمہ)
ٹی وی ڈرامے:۔
-1 توتا کہانی (1983ء)‘ -2 ایک محبت سو ڈرامے (1988ء)۔
ٹی وی پر ایک پروگرام ’’زاویہ‘‘ کے عنوان سے کیا جس میں ان کی گفتگو کو اسی نام سے چار جلدوں میں مرتب کرکے شائع کیا گیا۔ پنجابی نظموںکا مجموعہ ’‘کھٹیا وٹیا‘‘ بھی چھپ چکا ہے۔
…٭…
طاہر مسعود: آپ کا شمار ان ادیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تعداد کے اعتبار سے کم اور معیار کے لحاظ سے بہت اچھا لکھا ہے لیکن جب سے آپ نے ٹی وی کے لیے لکھنا شروع کیا ہے افسانہ نویسی قریب قریب ترک کر دی ہے۔ پھر آپ کے افسانوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ کبھی کبھی قاری کا جی چاہتا ہے کہ آپ سے پوچھے کہ آپ نے لکھنے میں اس قدر بخل کا مظاہرہ کیوں کیا ہے؟
اشفاق احمد: میں نے تعداد کے اعتبار سے اپنے ہم عصروں میں جتنا لکھا ہے شاید ہی کسی اور نے لکھا ہو۔ قاری تو بجا طور پر گلہ کر سکتا ہے کہ میں نے افسانے کم لکھے ہیں‘ لیکن سامع یا ناظر کو اس قسم کا شکوہ یقینا نہیں ہوگا۔ میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا متنازع ترین ڈراما نگار ہوں اور یہ ان معنوں میں خوشی کی بات ہے کہ لوگ میرے ڈرامے دیکھتے ہیں‘ سوچتے ہیں اور اختلاف بھی کرتے ہیں۔ میں اس لحاظ سے مطمئن ہوں کہ میں نے بہت کچھ لکھا‘ اس سے کم لکھ کر بھی اپنی بات کہی جاسکتی تھی۔ اگر میں نے افسانے کم لکھے ہیں تو دراصل یہ میری کوتاہی نہیں بلکہ میں نے کاغذ کی میڈیم کو چھوڑ کر الیکٹرانک کا میڈیم اختیار کر لیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الیکٹرانک کے میڈیم کا عہد ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے برسوں میں ایسی کتابیں مقبول ہوں گی جنہیں کیسٹ بک کہتے ہیں۔
طاہر مسعود: گویا آپ نے الیکٹرانک میڈیا کو چھپے ہوئے لفظ پر ترجیح دی ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا مثلاً ٹیلی ویژن کا اثر فوری تو ہوتا ہے لیکن چھپے ہوئے لفظ کی طرح دیرپا نہیں ہوگا۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے ایک تادیر قائم رہنے والی چیز پر ایک فوری مگر عارضی اثر رکھنے والی چیز کو اہمیت کیوں دی؟
اشفاق احمد: اس لیے کہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو مواد جمع ہو کر سامنے آ رہا ہے وہ کاغذ سے زیادہ دیر پا ہوگا۔ ولایت میں ایسی لائبریریاں عام ہو گئی ہیں جہاں وڈیو کیسٹ میں ڈرامے‘ افسانے‘ شاعری غرض یہ کہ ہر قسم کا ادب محفوظ ہے۔ چھپے ہوئے لفظ کے ساتھ گو ہمارا رابطہ پرانا ہے لیکن چھپا ہوا لفظ علم کو اس طرح عام نہیں کرتا جس طرح بولا ہوا لفظ (Spoken Word)کرتا ہے۔ لوک ورثے کی زبان میں اسے Oral Tradition کہتے ہیں۔ بابا بدھا کے زمانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک دانش کی ساری باتیں زبانی کہی گئی ہیں اور یہ بڑے علوم جو ہمیں ورثے میں ملے ہیں‘ اسے ایک سننے والے نے دوسرے سننے والے کو منتقل کیا اور بعد میں جب اسے محفوظ کرنے کا خیال آیا تو چمڑے پر‘ ہڈیوں پر اور درخت کے پتوں پر لکھ لیا گیا۔ علم آدمی کو آدمی کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے اور جو علم کتابوں میں محفوظ ہو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے اور جو آدمی کتاب لکھتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے۔ بظاہر یہ عجیب سی بات ہے لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ الفاظ اور تصورات کا بہت سا علم جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے معاشرے اور ماحول سے کٹ جاتا ہے۔ عمر کے اس اسٹیج پر پہنچ کر جب میں بحیثیت ادیب کے سوچتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ مجھے انسانیت سے بڑا پیار ہے اور انسان سے بڑی نفرت ہے اور ان انسانوں میں میر محمد اور خدا بخش جیسے تانگے والے اور رکشا ڈرائیور شامل ہیں جن سے میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ بس مجرد انسانیت سے دل بہلاتا رہتا ہوں۔ ہماری شاعری اور ادب اس مجرد انسانیت کے اظہار میں پیش پیش ہے۔
طاہر مسعود: آپ تسلیم کریں گے کہ ہر عمل کی بنیاد کسی خیال پر قائم ہوتی ہے اور خیال کے محفوظ رہنے کا پھیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ کتاب ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر انقلاب کے پیچھے ایک کتاب یا چند کتابیں موجود رہی ہیں لہٰذا کتاب کی اہمیت اور عمل سے اس کے تعلق سے منہ کیسے موڑا جا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے اشفاق صاحب! کہ بعض علوم مثلاً فلسفہ اور اخلاقیات خالصتاً کتابی علوم ہیں لیکن خالص ادب جس میں افسانہ اور ناول شامل ہیں‘ ان کا تعلق براہ راست زندگی کے تجربات و مشاہدات سے ہے‘ ان کے کردار کسی کتاب سے نہیں زندگی سے اخذ کردہ ہوتے ہیں لہٰذا کیا آپ انہیں مردہ (Dead) قرار دیں گے؟
اشفاق احمد: آپ کا یہ خیال کہ معاشرتی انقلاب کتابوں کے ذریعے آتا ہے‘ کسی خوش فہمی پر مبنی معلوم ہوتا ہے‘ انقلاب کتاب کی وجہ سے نہیں ہمیشہ صاحب کتاب کی وجہ سے آیا ہے۔ ہر انقلاب کے پیچھے ایک آدمی ہوتا ہے۔ اگر وہ آدمی نہ ہو تو کتاب کبھی انقلاب نہیں لا سکتی۔ کارل مارکس کی کتاب ’’داس کیپٹال‘‘ کے پیچھے سے آپ لینن‘ اسٹالن اور مائو کو ہٹا دیں تو ممکن ہے اس کتاب کی تفہیم میں نہایت فکر انگیز مقالات لکھ دیے جائیں لیکن انقلاب خواب و خیال ہو کر رہ جائے گا۔ آپ کی دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ بے شک ہم جن کرداروں کے بارے میں لکھتے ہیں وہ ہمارے دیکھے بھالے اور جانے پہچانے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ادب میں فلسفہ زندگی ہمیشہ کلیشے کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے اردو کے کسی ادیب نے انسانی زندگی کو مجموعہ اضداد کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا کیوں کہ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ دو صداقتیں یہ بیک وقت مختلف بھی ہو سکتی ہیں۔ ماحولیات میں مور بھی ہوتا ہے اورکوّابھی اور دونوں سچے ہوتے ہیں۔ ہاتھی کے خالق نے چیونٹی بھی تخلیق کی ہے۔ گھر کی دہلیز سے بیٹی کو رخصت کرنے والے باپ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں اور دل میں خوشی کے جذبات بھی اور ہم اسے منافق نہیں سکتے۔ اردو کے ادیبوں نے زندگی کو کبھی اس زاویہ نگاہ سے نہیں دیکھا۔ ترقی پسند تحریک سے بھی چند اچھے افسانوں کو خارج کر دیں تو ’’یتیم کے آنسو‘‘ اور ’‘بیوہ کی عید‘‘ کی سطح کے افسانے باقی رہ جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں اظہار اور گفتار پر پابندی ہے‘ اس لیے ادیب اچھا نہیں لکھ پاتے‘ سوچتا ہوں جس دن یہ پابندی نہ رہی تو شاید یہاں سے ارسطو اور افلاطون کے زمانے جیسی بلند پایہ تصانیف وجود میںآنے لگیں گی۔ ادیب حکومت کے خلاف لکھنا چاہتے ہیں‘ حالانکہ حکومت تو ایک چھوٹے درجے کی چیز ہے‘ بے معنی اور لایعنی‘ ادیب تو انسانی وجود کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس حوالے سے حکومت کا کر بھی بیچ میں آجائے تو اور بات ہے۔
طاہر مسعود: آپ نے افسانہ نگاری کے مقابلے میں ٹی وی میڈیا کا انتخاب اس لیے تو نہیں کیا کہ ادب کا دائرہ محدود ہو گیا ہے جب کہ ٹی وی کا دائرہ وسیع تر ہوتا جارہا ہے۔ آپ نےایک چھوٹے حلقے سے نکل کر (خواہ یہ چھوٹا حلقہ تعلیم یافتہ اور باشعور افراد پر ہی مشتمل کیوں نہ ہو) ایک بڑے حلقے کو چنا تاکہ آپ کی آواز دور تک پہنچ سکے۔
اشفاق احمد: بالکل یہی بات ہے۔ ادب غیر مؤثر اور محدود ہو گیا ہے۔ جب میں نے عام لوگوں کے لیے لکھنا شروع کیا تو اس کاجو ردعمل سامنے آیا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے سب سے پہلے ڈائجسٹ میں لکھا۔ میرے ادیب دوست ناراض ہوئے اور لعن طعن کی تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں نے کہا‘ نہیں‘ میں ان لوگوں کو جاننا چاہتا ہوں۔ ڈائجسٹ میں افسانہ چھپنے کے بعد مجھے اوکاڑہ سے ابراہیم درزی کا خط ملا۔ اس نے میرے افسانے پر نقید کی تھی۔ خط کی زبان تو ایسی ہی تھی لیکن اس میں بڑی فکر انگیز باتیں تھیں۔ 1967ء میں چین گیا جہاں چیئرمین مائو سے چند منٹ کی ملاقات کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا سر! ایک ادیب کی حیثیت سے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا میری نصیحت ہے کہ آپ اپنے ملک جائیں اور اپنے لوگوں کو علم عطا کریں اور ان سے علم حاصل کریں۔ میں نے افسردگی سے عرض کیا سر! میں تو آپ کا اتنا بڑا نام سن کر آیا تھا‘ آپ نے یہ کیسی عجیب بات کہی۔ میں تو ان لوگوں کو علم عطا کر سکتا ہوں‘لیکن پنو عاقل اور جھنگ شاہی کے لوگوں سے میں کیسے علم حاصل کروں‘ وہ تو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔ مائو نے کہا کہ پھر آپ ادب وغیرہ کا خیال چھوڑ دیں۔ (اشفاق صاحب کایہ خاص انداز گفتگو تھا۔ ضروری نہیں کہ مائو ان سے اور یہ مائوزے تنگ سے اسی طرح مخاطب ہوئے ہوں۔)
طاہر مسعود: خالص تخلیقی عمل میں ادیب کا ذہن اور روح آزاد ہوتے ہیں جب کہ ٹی وی جیسے سرکاری میڈیم کے اپنے مطالبات اور ان کی پالیسیاں ہوتی ہیں جن کا پابند ہونا پڑتا ہے‘ آپ اس میڈیم کے لیے لکھتے وقت اظہار کی راہ میں رکاوٹیں تو محسوس نہیں کرتے؟
اشفاق احمد: اظہار کی راہ میں رکاوٹیں تو ہمیشہ رہتی ہیں خصوصاً جب میڈیم پر سرکاری کنٹرول ہو‘ لیکن یہ کنٹرول تو ہر سطح پر ہے‘ مثلاً آدمی لوگوں کے درمیان رہتا ہے۔ اچھی اچھی‘ پیاری پیار اور گندگی گندی باتیں سوچتا ہے لیکن وہ سب کچھ لکھ نہیں سکتا۔ ادیب کو آزادیٔ اظہار کے لیے کسی چھوٹے بچے کی طرح ضد نہیں کرنی چاہیے۔ چھوٹا سا گٹکا کھیلنے والے بھی سو طریقے سے وار کر جاتے ہیں‘ ادیب کو بھی چاہیے کہ:
اِک رنگ کا مضموں ہے تو سو ڈھنگ سے باندھوں
ادیب کا کام آفاقی ہے۔ اسے یہ کہنا زیب نہیں دیتا کہ میرے راستے ہموار کرو‘ ان پہ بکھرے ہوئے کانٹے چن دو۔ پھر میں لانگ مارچ کروں گا‘ جیسا کہ میرے ایک ادیب دوست کا کہنا ہے کہ میں لانگ مارچ کر سکتا ہوں بشرطیکہ راستہ ائر کنڈیشنڈ ہو۔ جو ادیب پابندیوں کا عذر کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ تم ذرا اپنے کمرے میں چھپ کر لکھو اور پھر مجھے دکھائو کہ تم کتنا بڑا فلسفہ پیش کرتے ہو۔ پابندیاں ضرور ہیں اور ان پر کبھی کبھی خود سے گلہ بھی کر لینا چاہیے کہ دیکھو یا! اتنی چھوٹی سی بات کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن خواہ مخواہ کا ہیرو بننا کہ اگر مجھے آزادی مل جائے تو میں آئن اسٹائن کو بھی پیچھے چھوڑ دوں‘ فضول سی بات ہے۔
طاہر مسعود: ہماے ہاںدو قسم کے ادیب پائے جاتے ہیں‘ ایک کُل وقتی ادیب دوسرے جزوقتی۔ آپ ایک ادارے کے سربراہ اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے اسکرپٹ رائٹر ہیں۔ آپ نے کن وجوہ کی بنا پر صرف ادیب رہنا پسند نہیں کیا؟
اشفاق احمد: اگر میں ریلوے کا گارڈ ہوتا تو آپ یہ سوال مجھ سے پوچھ سکتے تھے لیکن میں نے تو صرف ادیب رہنا ہی پسند کیا ہے اور اسی ناتے سے موجودہ عہدہ مجھے ملا ہے اور یہ عہدہ بھی میں نے اس لیے قبول کیا ہے کہ صرف لکھ کر میں اتنے پیسے نہیں کما سکتا تھا کہ گھر کے اخراجات پورے ہو جاتے۔ بعض ادیب روزگار کے لیے صحافت کا سہارا لیتے ہیں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن بھی اسی ذیل میں آتے ہیں حالانکہ ان سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی جتنی کہ سمجھی جاتی ہے‘ مثلاً پچاس منٹ کے ایک کھیل کا معاوضہ گیارہ سو روپیہ ملتا ہے اور ایک طویل سیریز کے چودہ پندرہ ہزار روپے بن جاتے ہیں۔ دوسروں کو میں اپنے ایک ڈرامے کا معاوضہ دس ہزار روپے بتاتا ہوں۔ یہ سن کر وہ میری عزت کرنے لگتے ہیں۔ بچوں سے کہتے ہیں پیچھے ہٹو!شاہ صاحب آرہے ہیں۔
طاہر مسعود: آپ نے لکھنے اور مطالعہ کرنے کا کیا طریقہ کار متعین کیا ہے‘ ان پر کتنا وقت صرف کرتے ہیں؟
اشفاق احمد: یہ ہمہ وقتی پیشہ ہے۔ میں پڑھنے میں آہستہ رو ہوں‘ البتہ لکھنے کے معاملے میں خاصی تیزی ہے۔ دن میں دفتری کاموں کے بعد میرے پاس رات باقی رہ جاتی ہے‘ جسے میں اپنی مرضی سے مصرف میں لاتا ہوں۔ ڈراما لکھنے کا طریقہ کاریہ ہے کہ میں پہلے سے نوٹس تیار کرکے رکھ چھوڑتا ہوں‘ اس طرح لکھتے وقت مجھے صرف کیلیں ٹھونکنی پڑتی ہیں‘ یہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ پچاس منٹ کا ایک ڈراما تین دن میں لکھا جاتا ہے بشرطیکہ نوٹس تیار ہوں‘ ان تین دنوں میں کانٹنا‘ چھانٹنا اور ان راستوں سے بچنا بھی شامل ہے جن پر پکڑے جانے کا اندیشہ ہو جیسے آپ لوڈو کھیلتے ہیں اور فریق مخالف کی گوٹ سے اپنی گوٹ بچا کر نکالتے ہیں۔
طاہر مسعود: صبح کے وقت آپ لکھنے کا کام نہیں کرتے؟
اشفاق احمد: میں نے کئی دفعہ صبح لکھنے کی کوشش کی‘ منہ اندھیرے اٹھ گیا‘ لیکن لکھ نہیں سکا۔ رات ہی مناسب ہے‘ جوں جوں خاموشی ہوتی اور بھیگتی جاتی ہے‘ لکھنے میں آسانی محسوس ہوتی ہے۔
طاہر مسعود: لکھنے کے بعد آپ کی تحریر سیلف ایڈیٹنگ کے مرحلے سے بھی گزرتی ہے؟
اشفاق احمد: میں ایک دفعہ لکھتا ہوں۔ کوئی فقرہ اگر دل کو نہیں لگتا تو مسودے پر ہی کاٹ کر درست فقرہ لکھ دیتا ہوں۔
طاہر مسعود: مثلاً ’’سفر در سفر‘‘ آپ نے کس طرح لکھا؟
اشفاق احمد: اسے میں نے اس طرح لکھا ہے جیسے کسی کو خط کا جواب لکھا جا رہا ہو۔ میں نے کسی موقع پر بھی دوبارہ مڑ کر نہیں دیکھا کہ پچھلے باب میں کیا لکھا تھا۔ یہ کتاب تو جیسے اعصاب پر سوار ہو گئی تھی۔
طاہر مسعود: آپ کا مشہور افسانہ ’’گڈریا‘‘ کے بارے میں آپ نے کہیں لکھا تا کہ اسے آپ نے روم کے ایک پوسٹ آفس پر ڈاک کے حوالے کرنے سے قبل مکمل کیا تھا؟
اشفاق احمد: وہ ایک عجیب قصہ تھا۔ میں اُن دنوں روم میں تھا اور یونیورسٹی میں اردو پڑھانے پر مامور تھا۔ مدیر ’’نقوش‘‘ نے اپنے خط میں افسانے کا تقاضا کیا۔ بڑی مصروفیت کے دن تھے۔ ذہن میں کہانی کا ایک خاکہ تھا‘ اسے میں نے لکھنا شروع کیا۔ مسودہ ہر وقت میرے پاس رہتا اور جہا ںموقع ملتا‘ لکھنے بیٹھ جاتا۔ غرض کئی نشستوں کے بعد یہ تقریباً مکمل ہو گیا۔ ارادہ تھا کہ آخری دو پیرا گراف پوسٹ آفس میں لکھ لوں گا اور پھر اسے حوالۂ ڈاک کر دوں گا لیکن وہاں جو کہانی ختم کرنے کی کوشش کی تو وہ مزید پھیلتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ کھڑے ہو کر لکھتے لکھتے میرے گھٹنے شل ہو گئے۔ میں اسے گھر لے آیا اور اختتام کو پہنچایا لیکن اس افسانے کو پوسٹ کرنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ اس کے اندر کئی جگہ جھول رہ گیا ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا کہ وہ جا کر طفیل صاحب سے ملے اور ان سے افسانہ لے کر مجھے بھیج دے تاکہ میں اسے مزید بہتر بنا سکوں۔ دوست کا جواب آیا کہ طفیل صاحب تمہارے افسانے سے بے حد خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا اچھا افسانہ تو ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہی نہیں۔ خیر یہ افسانہ چھپا تو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کی اکہ اچھا ہوا کہ اسے دوبارہ نہیں دیکھا‘ ورنہ پتا نہیں اس افسانے ض کیا گت بنتی۔
طاہر مسعود: آپ کی کہانیوں کے بیش تر کرداروں سے آپ کی ملاقات رہی ہے یا ان میں سے زیادہ تر آپ کے تخیل کی پیداوار ہیں؟
اشفاق احمد: دونوں ہی صورتیں رہی ہیں لیکن میں آپ سے ایک بات کہوں کہ جو کردر آپ کے مشاہدے میں آتے ہیں اگر آپ انہیں من و عن پیش کرنے کی کوشش کریں تو بہت … اور بے چاری ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان کرداروں میں اسی وقت زندگی پیدا ہوتی ہے جب ادیب اسے اپنا فلسفہ دینا چاہتا ہے۔ میں کالو بھنگی کو دیکھتا ہوں اور اب میرا کام یہ ہے کہ میں اسے ایک کردار اور وژن عطا کروںکیوں کہ ادب اسی صورت میں تخلیق ہو سکتا ہے۔ سوال صرف اتنا سا ہے کہ آپ اپنے کردار کے ذریعے کس بات کی سکھشا دینا چاہتے ہیں؟ بابو گوپی ناتھ یقینا کوئی شخص رہا ہوگا‘ مگر وہ بابو گوپی ناتھ نہیں ہوگا جسے منٹو نے پیش کیا۔ بعض ادیبوں نے بہت اچھے کردار بعینہ پیش کیے جنہیں پڑھ کر قاری نے سوچا کہ اس سے تو یہ جیتا جاگتا کردار اچھا تھا۔
طاہر مسعود: اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ افسانہ نگار جس کردار کے بارے میں لکھتا ہے اسے پہلے خود پر طاری کر لیتا ہے یا وہ کردر خود بن جاتا ہے‘ اس میں کتنی صداقت ہے؟
اشفاق احمد: یہ بڑی غور طلب ہے۔ بانو قدسیہ نے اپنی کتاب کی تقریب رونمائی میں ایک بات کہی اور اس پر بڑی لے دی ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ادیب بنیادی طور پر بڑا کمینہ ہوتا ہے‘ وہ اتنے اعلیٰ درجے کا تھرما میٹر ہوتا ہے کہ وہ جس کردار کو پکڑتا ہے اس کے ساتھ کمینگی میں پورے طور پر شریک ہوتا ہے مثلاً وہ چور کے بارے میں لکھے گا تو چور تو ہوگا ہی جبھی تو چوری کی باریکی کو سمجھ رہا ہے۔ وہ کنجوس کے متعلق لکھتے وقت اتنا ہی کنجوس بھی ہوگا اسی لیے وہ کنجوسی کی جزئیات سے واقف ہوگا۔ بانو قدسیہ نے ادیب کی بنت کی جو تعریف پیش کی تھی اس پر ادیبوں کے حلقے کی جانب سے ان کی بے حد سرزنش ہوئی اور کہا گیا کہ ادیب تو نہایت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے‘ وہ تو فرشتوں کی طرح معصوم اور ستاروں کی طرح خوب صورت ہوتا ہے۔ بانو قدسیہ نے اس کے جواب میں نہایت دل چسپ بات کہی کہ جو ادیب بہت نیک‘ پارسا اور شریف ہوتے ہیں‘ وہ نہ تو معروف ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی چیزیں کوئی پڑھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بانو کا استدلال بالکل درست تھا۔ جب کسی آدمی کو اللہ کی طرف سے ادیب بنانے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ حسیّت یا وہ کمینگی از خود پیدا ہو جاتی ہے۔
طاہر مسعود: آپ کو یاد ہے کہ آپ نے لکھنا کب سے شروع کیا؟
اشفاق احمد: مین نے چھٹی یا ساتویں جماعت ہی میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اسی زمانے میں‘ میں نے ایک پرچہ بھی نکالا تھا جس کا نام ’’علم الوقیع‘‘ رکھا تھا۔ اس کی ایک ہی کاپی چھپتی تھی۔ اس کا ایڈیٹر‘ پبلشر اور قاری سب کچھ میں ہی تھا۔ اخباروں کے ٹکڑے لے کر چھ صفحے کا ایک پرچہ ہر مہینے چھاپتا تھا اور اسے سب سے چھپا کر رکھتا تھا۔ میرا پہلا باقاعدہ افسانہ ’’توبہ‘‘ 1942ء میں ’’ادبی دنیا‘‘ میں چھپا۔ یہ میرا پہلا افسانہ تھا۔ پہلے میں نے اسے ’’ساقی‘‘ نئی دہلی بھیجا لیکن شاہد احمد دہلوی کا خط آیا کہ آپ کا افسانہ معیار پر پورا نہیں اترا اس لیے شکریے کے ساتھ واپس۔ میں حیران ہوا‘ تھوڑی سی مایوسی بھی ہوئی۔ پھر میں نے اسے ’’ادبی دُنیا‘‘ میں مولانا اصلاح الدین احمد کو بھیج دیا۔ ان کا خط آیا کہ تمہارا افسانہ نہایت کمال کا ہے اور تم کبھی لاہور آنا تو مجھ سے ضرور ملنا۔ اس افسانے پر انہوں نے ادارتی نوٹ بھی لکھا۔ اس کے بعد مختلف ادبی رسائل میں چھپنے لگا۔ ساقی‘ نقوش‘ ادبِ لطیف‘ سنگ میل وغیرہ۔
اب میں اپنے افسانوں کو دیکھتا ہوں تو آپ کے پہلے خیال کی تصدیق کرنی پڑتی ہے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ مجھے اور افسانے لکھنے چاہئیں تھے۔ میں آپ کو ایک اطلاع دیتا ہوں کہ میں نے چند روز قبل فیصلہ کیا ہے کہ میں مزید افسانے لکھوں گا۔ یہ تازہ اور نئے افسانے ہوں گے‘ تکنیک اور کہانی کے اعتبار سے۔ ان میںسے چند علامتی افسانے ہوں گے‘ چند حیران کر دینے والے اور چند عہد جدید کی ضروریات کے مطابق چیخ و پکار سے بھرپور‘ انہیں میں ڈسکو ٹائپ افسانے کہتا ہوں۔ کل ہی میں انتظار حسین سے کہہ رہا تھا کہ بھئی ہمیں اسی پرانی وضع کے افسانے لکھنے ہوں گے۔ یہ افسانے میں کسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے لکھوں گا کہ اس سے مجھے خوشی ہوگی۔
طاہر مسعود: لکھنے کی ابتدا کی تو سب سے زیادہ کس ادیب کو پڑھا؟
اشفاق احمد: ہمارے دور میں کرشن چندر عروج پر تھے لیکن جس ادیب کو میں نے کثرت سے پڑھا ہے وہ راجندر سنگھ بیدی ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس سے بڑا شارٹ اسٹوری رائٹر اردو میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ بیدی گرو ہے۔ اب بھی موقع ملے تو میں اسے پڑھتا ہوں۔
طاہر مسعود: عام خیال ہے کہ منٹوکا فن بیدی کے فن سے بڑا ہے؟
اشفاق احمد: منٹو میرے عزیز دوستوں میں سے تھے لیکن وہ بیدی کی گرد کو بھی نہیں پہنچتے۔ بیدی کو کم لوگ پڑھتےہیں۔ کوئی صاحبِ نظر آدمی ہی اسے پڑھتا ہے۔ غیر ملکی ادب میں‘ میں نے بہت سوں کو پڑھا ہے لیکن جو بات دوستوفیسکی میں پائی‘ کہیں اور نظر نہیں آئی۔ اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ میں ’’ایڈیٹ‘‘ کو تیسری دفعہ پڑھ رہا ہوں‘ کالج کے زمانے میں یہ ناول مجھے اور طرح کا لگا تھا۔ پھر جب میں نے خود لکھنا شروع کیا تو اس نے مجھے بالکل دوسرے طریقے سے متاثر کیا اور جب کہ میں ساٹھ سال کی عمر میں اسے پڑھ رہا ہوں تو یہ کچھ اور ہی طریقے سے دل میں اتر رہا ہے۔
طاہر مسعود: ’’سفر در سفر‘‘ پڑھ کر سوال پیدا ہوا کہ آپ نے ناول نویسی کی طرف توجہ کیوں نہیں دی؟ خصوصاً اس شکایت کے پس منظر میں کہ اردو میں اچھے ناولوں کی کمی ہے۔
اشفاق احمد: اس سوال کا جواب آپ کے پچھلے سوال میں مضمر ہے اور وہ یہ کہ میں ایک نوکر پیشہ آدمی ہوں‘ باوجود اس کے کہ لکھنے پڑھنے کا کام ہے‘ لیکن پھر بھی گھر گرہستی کو چلانا اور نوکری کے تقاضوں کو پورا کرنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ اگر میں ایک ماتحت کی حیثیت سے ملازم ہوتا تو شاید آسانی رہتی۔ ناول نویسی کے لیے اپنے آپ کو باندھ کر یک جا رکھنا پڑتا ہے۔ افسوس کہ باوجود خواہش کے‘ میں ایسا نہ کرسکا لیکن جیسا کہ میں نے افسانے کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اب افسانہ لکھنے کو جی چاہنے لگا ہے۔ اسی طرح خیال ہے کہ بہت طویل نہیں تو چھ سات سو صفحے کا ایک ناول لکھنا جانا چاہیے۔ ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکا ہوں کہ یہ ناول کس زاویہ نگاہ سے لکھوں‘ کس مضوع پر لکھوں؟ اگر مجھے وقت ملا اور میں جلدی ریٹائر کر دیا گیا‘ فرض کیجیے دسمبر تک تو مجھے ناول لکھنے کا موقع مل جائے گا۔
طاہر مسعود: بہ حیثیت ادیب کوئی ایک سوال جو آپ کو ستاتا ہو اور ہر وقت آپ کے تعاقب میں ہو؟
اشفاق احمد: میں ایک ہی بات کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھا ہوں کہ انسان کی جدوجہد ہمیشہ اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ یہ کوششں اور سعی و جستجو انسان کے عزائم کو تکمیل تک نہہں پہنچاتے لیکن میں اس جدوجہد کو اس لیے چھوڑنے کے حق میں نہیں ہوں کیوں کہ اس سے دل لگانا ہے مثلاً تاش کھیلنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے لیکن اس کی افادیت بس اتنی سی ہے کہ مشکل وقت آپ کا دل منہمک رہتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ انسان کی تقدیر کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں‘ ان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا انسان کا شیوہ نہیں ہے۔ میں صرف دو چیزوں کا قائل ہوں یا تو انسان تحیر میں رہے یا شدید غم میں ڈوبا ہو۔ جو شخص چڑ اور احتجاج میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ Protester تو اچھا بن سکتا ہے لیکن ادیب نہیں بن سکتا۔ وہ کہے کہ یہ میرا غم ہے اور پھر یہ غم اسے کھاتا رہی تبھی وہ تخلیقی آدمی بن سکتا ہے۔ تخلیق کا غم سے بہت گہرا تعلق ہے اس کی ابتدا تحیر سے ہوتی ہے اور انتہا غم پر۔
طاہر مسعود: ’’محبت‘‘ آپ کا پسندیدہ موضوع ہے۔ اپنے افسانوں اور ڈراموں میں آپ نے اس موضوع کو جن زایوں سے دیکھا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس موضوع نے آپ کو اتنا متاثر کیوں کیا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص واقعہ پوشیدہ ہے؟
اشفاق احمد: شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں گائوں میں رہتے تھے۔ گائوں کے لوگ کچھ گھامڑ اور سیدھے ہوتے ہیں۔ باوجود کھردرے اور کرخت ہونے کے ان میں محبت کا عجیب سا انداز ہوتا ہے مثلاً گائوں کی ایک اَن پڑھ ماں جو اپنے بچے کو پھٹے پرانے کپڑوں میں لیے پھرتی ہے‘ ایسی محبت مجھے شہروں میں نظر نہیں آئی۔
جب میں یونیورستی کا علم حاصل کر چکا اور لکھنا شروع کیا تو محبت ہی کے موضوع پر لکھتا رہا۔ بچے کی کھلونے یا کتے سے محبت‘ یا نانی اماں کی اپنے پوتے سے محبت۔ یہ لوگ محبت کرتے سمے کبھی یہ نہیں کہتے کہ وہ محبت کر رہے ہیں۔ اس کا اظہار تو ان کے رویے سے ہوتا ہے۔ میں نے بچپن میں محبت کے جتنے مظاہر دیکھے تھے جب انہیں لکھ چکا تو عمر کے اس مرحلے میں مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں بابا لوگوں کے پاس جائوں۔ پھر مزاروں پر فقیروں کے ڈیرے پر جانے لگا۔ ان کے ہاں بھی میں نے یہی دیکھا کہ سب سے زیادہ جلوہ محبت ہی کا کارفرما ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں صوفی بن گیا ہوں۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ میں تو ان لوگوں کو دیکھ کرتحیر میں مبتلا ہوں۔ میں نے محبت کرنے والے گیارہ آدمیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور جتنے لکھنے والے ہیں ان میں شاید ہی کوئی ایسا خوش نصیب ہوگا جس نے تین‘ چار محبت کرنے والے بھی دیکھے ہوں۔ محبت کرنے والے سے مراد ہیر رانجھا اور سوہنی مہینوال نہیں ہیں بلکہ وہ محبت ہے جو صلے اور ستائش کی تمنا سے بے نیاز ہو کر خلق خدا سے کی جائے۔ میرے ایک بابا ہیں۔ بابا فضل شاہ۔ میں نے ایک بار ٹٹولنے کی غرض سے ایک شخص کے خلاف انہیں انگیخت کیا اور کہا کہ وہ بڑا مکار شخص ہے اور آپ کی عدم موجودگی میں آپ کو برا بھلا کہتا رہتا ہے اور اب کی اس نے ایسا کیا تو ہم اسے زدوکوب کریں گے۔ بابا نے جواب دیا ’’نہیں‘ وہ برا آدمی نہیں ہے‘ وہ صرف علم کی کمی کی وجہ سے ایسا ہے لہٰذا اسے تم برا نہ کہو۔‘‘ دیکھیے یہ محبت کی وہ شکل ہے کہ جب آدمی اس میں ایک بار مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس محبت کی حالت میں وہ فوت ہوتاہے۔ فوت نہیں ہوتا‘ امر ہو جاتا ہے۔