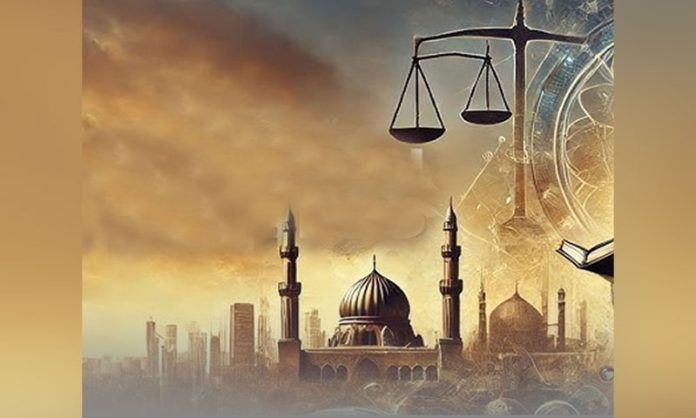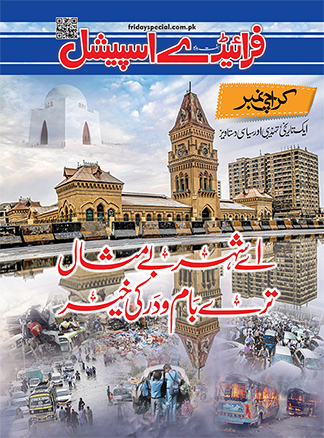ہم اپنی مذہبی فکر، تہذیب اور اپنے مفکرین کی فکر کی تاریخ سے کتنا دور ہوگئے ہیں
سیاست ایک مقدس مقام ہے لیکن ہمارے یہاں یہ مقام ایسے تھان میں تبدیل ہوگیا ہے جہاں آصف زرداری اور نوازشریف جیسی مخلوقات کھونٹے سے باندھی جاتی ہیں، اور نہ صرف باندھی جاتی ہیں بلکہ انھیں ہر طرح کا چارہ بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کھونٹے سے باندھنے والے پھر انھیں رسّا توڑ کر بھاگنے پر مائل یا مجبور بھی کرتے ہیں اور اس کی داد پاتے ہیں۔ اس سے بھی المناک بات یہ ہے کہ اس تھان سے فضلہ اٹھانے کے کام میں بڑے بڑے دانشور، صحافی، تجزیہ نگار اور مبصرین حصہ لیتے ہیں، فرق یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی جمہوریت کے اوزار استعمال کرتا ہے، کوئی قومی مفادات کے آلات بروئے کار لاتا ہے اور کوئی عام دلائل کے پنجر اور جھاڑو استعمال کرتا ہے۔ اس صورتِ حال نے عوام اور خواص یا ان کی ایک بڑی تعداد کے لیے سیاست کو ایک گالی بنادیا ہے، لوگ برملا کہتے ہیں کہ سیاست شریفوں کا کام نہیں، اور عزتِ سادات بچانی ہے تو سیاست کے کوچے سے گریز ہی بہتر ہے۔ عوام کا یہ ردعمل سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ عوام کی کوئی ذہنی سطح ہی نہیں ہوتی۔ لیکن مسئلہ تو خواص کا ہے جو خود کو تعلیم یافتہ اور باشعور قرار دیتے ہیں اور سیاست کے بارے میں یہ عوام کی سطح سے بھی گری ہوئی باتیں کرتے ہیں۔ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ان کی مذہبی فکر میں سیاست کا کیا مقام ہے اور مسلم مفکرین کیعظیم اکثریت نے اس بارے میں کیا کہہ رکھا ہے۔
فکر کے حوالے سے اُمتِ مسلمہ کے محسنوں کی فہرست مرتب کی جاتی ہے تو امام غزالیؒ کا نام سرفہرست ہوتا ہے۔ وہ عالمِ دین تھے، متکلم تھے، صوفی تھے، فلسفی تھے، غرضیکہ کیا نہیں تھے! غزالی نے صرف 55 سال عمر پائی لیکن اتنی سی عمر میں انھوں نے علم کا بحرِ ذخار پیدا کرکے دکھا دیا۔ لیکن زیربحث موضوع کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ غزالی نے علوم کی تقسیم کی تو ایک فہرست میں انھوں نے ریاضی، منطق اور طبعیات وغیرہ کو رکھا ہے، اور دوسری فہرست میں جنھیں وہ شرع سے متعلق علوم کی فہرست کہتے ہیں انھوں نے سیاست کو مابعدالطبعیات، علم الاخلاق اور علم النفس کے ساتھ رکھا ہے۔ غزالی نے صاف لکھا ہے کہ علمِ سیاسیات انبیا اور رسل پر نازل ہونے والی آسمانی کتابوں سے حاصل ہوتا ہے یا پھر سیاست کے اُصول سلف صالحین کے احکامات و اقوال سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے المنقذ من الضلال میں سیاست کے معاملات و مسائل پر تفصیل سے اظہارِ خیال کیا ہے۔ غزالی کی ایک اور تصنیف بہترالمسبوک ہے جس میں سیاسیات و اخلاقیات کو موضوع بنایا گیا ہے۔ لیکن غزالی کی ایسی کئی تصانیف ہیں جو براہِ راست سیاست کے موضوع سے تعلق نہیں رکھتیں مگر اس کے باوجود اُن میں وہ جگہ جگہ سیاست پر کلام کرتے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ خالصتاً عقائد کے بارے میں لکھی گئی کتاب میں جابجا سیاسی اصول بیان کیےگئے ہیں۔
ابونصر فارابی جیسی نادر روزگار شخصیات زمانے نے کم ہی دیکھی ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 20 زبانیں جانتا تھا اور دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا موضوع ہوگا جس پر فارابی نے کلام نہ کیا ہو۔ ارسطو کو فلسفے کی روایت میں معلم اوّل کہا گیا ہے، ابونصر فارابی چونکہ ارسطو کا شارح تھا، اس لیے اسے معلم ثانی قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ وہ ارسطو اور افلاطون کا مقلد تھا لیکن اس نے جابجا ان کی فکر میں اضافے بھی کیے ہیں۔ اگرچہ اس کی شہرت فلسفے کے حوالے سے ہے، لیکن اس نے سیاسیات کو غیر معمولی اہمیت دی ہے اور اس سلسلے میں اُس نے دو اہم تصانیف سیاست المدنیہ اور آرا اہل مدینۃ الفاضلۃ چھوڑی ہیں۔ اس نے افلاطون کی ”جمہوریہ“ سے متاثر ہوکر مثالی ریاست کا تصور پیش کیا ہے لیکن اس کی تصنیف میں ایسے عنوانات بھی ملتے ہیں جن کا ”جمہوریہ“ میں کوئی ذکر نہیں۔
جہاں تک ماوردی کا تعلق ہے تو ان کی شہرت کا مدار ہی ان کے سیاسی تصورات پر ہے۔ ان کا استدلال اسلامی ہے اور وہ قرآن و سنت کو سرچشمہ ہدایت تصور کرتے ہیں۔ انھوں نے جہاں جہاں ریاست اور حکمرانوں کے معاملات پر بحث کی ہے، قرآن و سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال تابعین اور تبع تابعین کے فرمودات کے حوالے سے پیش کیے ہیں۔ سیاست سے اس شیفتگی کے باعث ماوردی کو پہلا مسلم سیاسی مفکر بھی قرار دیا گیا ہے۔
ابنِ خلدون کی شہرت ایک ماہرِ عمرانیات کی ہے لیکن اس نے سیاست اور ریاست کے معاملات پر گراں قدر خیالات پیش کیے ہیں۔ سیاسی نظاموں کی بحث اُٹھاتے ہوئے ابنِ خلدون نے صاف لکھا ہے کہ خلافت کا نظام بہترین ہے، کیونکہ یہ نظام دنیوی اور خالص سیاسی بنیادوں کے بجائے دینی اوامر و نواہی پر استوار ہوتا ہے۔ ابنِ خلدون نے اس رائے سے اختلاف کیا ہے کہ حکمران زمین پر خدا کا خلیفہ ہے۔ اس کے برعکس اُس کا خیال ہے کہ حکمران رسول کا خلیفہ ہے- لیکن اس نے صاف کہا ہے کہ خلافت اُس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک لوگوں کے دلوں میںدین کا احترام باقی رہتا ہے۔
مسلم مفکرین کی یہ فہرست طویل ہے اور اس میں طوسی سے ابنِ تیمیہ، اور ابنِ تیمیہ سے مولانا مودودی تک بہت سے نام آتے ہیں۔ یہاں تک کہ ابنِ عربی نے جنھیں صرف عرفان، تصوف اور مابعدالطبعیات یا ”علم اعتباری“ سے متعلق سمجھا جاتا ہے، سیاست پر کلام کیا، اور اگر ہمیں ان کی کتب کی فہرست کے عنوانات ٹھیک طرح یاد ہیں تو انھوں نے سیاسیات کے موضوع پر ایک رسالہ بھی چھوڑا ہے۔ یہ صورتِ حال سیاست کی مرکزیت و اہمیت پر ہی دال نہیں بلکہ اس سے سیاست کے تقدس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ ہمارے یہاں سیاست ایک حقیر چیز بن کر رہ گئی ہے۔ ”ہمارے یہاں“ سے مراد ظاہر ہے کہ صرف پاکستان نہیں، بلکہ پوری امتِ مسلمہ کا کم و بیش یہی معاملہ ہے۔ یہ منظرنامہ اس امر پر گواہ ہے کہ ہم اپنی مذہبی فکر، تہذیب اور اپنے مفکرین کی فکر کی تاریخ سے کتنا دور ہوگئے ہیں۔
اس صورتِ حال کا صرف یہی نتیجہ برآمد نہیں ہورہا کہ سیاست کو ایک منفی سرگرمی سمجھا جارہا ہے، بلکہ بعض لوگ سیاست کو گفتگو کے لائق بھی نہیں سمجھتے۔ ہمارے درمیان ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہوچلا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ سیاست فرد کے لیے ”درجہ کمال“ کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس طبقے کا خیال ہے کہ سیاست میں پڑکر انسان سیاست باز ہوجاتا ہے۔ یہ خیال ایک حد تک درست بھی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان سیاست باز کیا ’’تصوف باز“ بھی ہوسکتا ہے… کبوتر باز، پتنگ باز اور اُصول باز بھی۔ سیاست بازی، تصوف بازی، اصول بازی، پتنگ بازی اور کبوتر بازی میں کیا جوہری فرق ہے؟ اس سوال پر ہم نے بہت غور کیا لیکن کوئی خاص فرق تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ آپ کو ان چیزوں میں کوئی فرق نظر آتا ہے تو ہمیں ضرور بتائیے۔