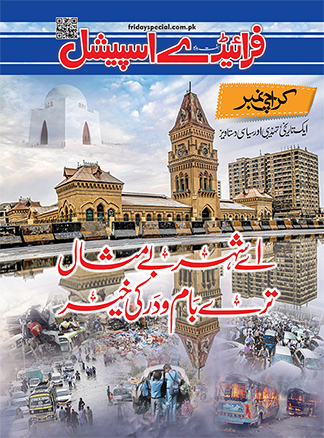ژاں پال سارتر نے کہا ہے کہ ’’دوسرے‘‘ (ہمارا) جہنم ہیں۔ یہ تصور مغربی فکر میں متعین انسان کی تعریفات کے عین مطابق ہے۔ مغربی فکر کا فرد ایک آزاد اور خودمختار ریاست کی طرح ہے۔ ایسی ریاست کی طرح جو دوسری ریاستوں سے ’’سفارتی‘‘ تعلقات رکھتی ہے اور وہ کسی دوسری ریاست کو اپنی حدود میں در آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ افراد کے درمیان سفارتی تعلقات کی بات مذاق نہیں۔ زندگی کا تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایک دوسرے کے ساتھ ایسی زبان میں گفتگو کرنے لگی ہے جس سے سفارت کاری کی بو آتی ہے۔ انسان کی گرم جوشی اور سردمہری، ہم مشربی اور کشیدگی پر بھی سفارت کی مہر کو صاف طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ ایک عجیب منظر ہے کہ ایک جانب جذبات و خیالات کی شدت بڑھتی نظر آرہی ہے اور دوسری جانب ان کی گہرائی عنقا ہوتی جارہی ہے۔ ان دونوں رجحانات میں اِرتباطِ باہمی کی نشاندہی ہونی چاہیے، لیکن جس شدت کی ہم بات کررہے ہیں اس کا تعلق گہرائی سے نہیں سطحیت سے ہے اور سطحیت سفارتی تعلقات کا دوسرا نام ہے۔
آزاد اور خودمختار ریاست کا تصور بظاہر بڑا متاثر کن معلوم ہوتا ہے، لیکن ہماری مذہبی فکر میں انسان کو کائناتِ اصغر کہا گیا ہے۔ کائناتِ اصغر کے مقابلے پر خودمختار ریاست کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ کائنات کوئی خودمکتفی کائنات نہیں بلکہ اس کا اپنی جیسی دوسری کائناتوں اور خود کائناتِ اکبر سے بہت گہرا تعلق ہے اور اس کے وجود کی پوری معنویت اسی تعلق سے متعین ہوتی ہے۔ لیکن اس عہد کا المیہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے کائناتِ اصغر نہیں، خودمختار اور آزاد ریاست ہونے پر اصرار ہے اور اس کا خیال ہے کہ اِس آزاد اور خودمختار ریاست کو فی نفسہٖ کسی دوسرے وجود کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص اپنے لیے کافی ہے۔ ذرا مغربی دُنیا کے منظرنامے کو دیکھیے۔ والدین کو اولاد کی، اور اولاد کو والدین کی ضرورت نہیں۔ اور اگر یہ ضرورت ہوتی بھی ہے تو ایک عرصے کے بعد گویا ختم ہوجاتی ہے۔ خاندان کے ادارے کے بعد وہاں شادی کا ادارہ بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شادی طلاق حاصل کرنے کے ایک بہانے کے سوا کچھ نہیں۔ چناں چہ وہاں عارضی اور تجرباتی تعلق کا رجحان سکہ رائج الوقت بن گیا ہے جو شادی کے ادارے کی نفی کے مترادف ہے۔ مغرب جنسی زندگی کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ مغرب میں لوگ شوہر اور بیوی نہیں، بلکہ صرف مرد اور عورت ہوتے ہیں، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ عرصے کے بعد وہاں مرد اور عورت کو بھی ایک دوسرے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ صورتِ حال دوسرے کو اپنے وجود کی سرحد سے دور کردینے اور اسے اپنے وجود کے دائرے میں در آنے سے روکنے کی شعوری یا لاشعوری خواہش ہی کا نتیجہ ہے۔ تو کیا دوسرے واقعتاً ہمارا جہنم ہیں؟ کیا ہمیں دوسروں کی ضرورت نہیں؟ کیا دوسرے ہماری زندگی میں مداخلتِ بے جا کے مرتکب ہوتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے وجود کے ارتقا کی راہ میں رکاوٹ ہیں؟ ہم میں بیشتر افراد یقیناً اِن تمام سوالات کا جواب نفی میں دیں گے۔ اس لیے کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مقدس کتابوں، رسولوں اور نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم دینِ حنیف کے پیروکار ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم دوسری بہت سی چیزوں کی طرح زیربحث موضوع اور رجحانات کے حوالے سے بھی مغرب کے زیراثر آچکے ہیں۔ ہم تسلیم کریں یا نہ کریں، ہم بھی ’’دوسرے‘‘ کو اپنے لیے عذاب سمجھنے لگے ہیں، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے سیکڑوں مظاہر اس کا ثبوت ہیں۔ ناقابلِ تردید ثبوت۔ ہم مذاہب، ممالک، صوبوں، زبانوں، علاقوں، مکاتب فکر اور سیاسی نقطہ ہائے نظر کے حوالے ہی سے نہیں، والدین اور اولاد، شوہر اور بیوی، بہن، بھائی، عزیزوں اور احباب کی سطح پر بھی ’’دوسرے‘‘ کے مسئلے کا شکار ہوچکے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دوسرے کا مطلب غیر یا اجنبی نہیں۔ تو کیا دوسرے واقعتاً ہمارا جہنم ہیں؟ کیا ہم سب خودمختار اور آزاد مملکتیں ہیں؟ کیا دوسرے ہمارے راستے کی دیوار ہیں؟
یہ ایک بہت رسمی اور سامنے کی بات ہے کہ انسان اپنی پیدائش کے بعد بہت عرصے تک زندہ رہنے کے لیے ’’دوسروں‘‘ کا محتاج ہوتا ہے۔ ان دوسروں میں صرف اس کے خاندان کے لوگ ہی نہیں، دوسرے بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کو بھول جانے کا مرض لاحق ہے۔ اسے کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ وہ کسی کو اپنا محسن تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اس کے رویوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے وہ خود ہی بڑا ہوگیا۔ انسان بڑا ہوجاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب اسے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن انسانوں کی بہت بڑی تعداد ان لوگوں پر مشتمل ہے، جن کی مسرتیں دوسروں کی مرہونِ منت ہوتی ہیں۔
انسان کامیاب ہوتا ہے اور کامیابی پر خوش ہوتا ہے، لیکن اس کی خوشی محض کامیابی کی خوشی نہیں ہوتی، اس میں خودنمائی یا Vanity کا عنصر بھی ہوتا ہے، جو ہمیشہ دوسروں کی وجہ سے اور دوسروں ہی کے لیے بروئے کار آتا ہے۔ انسان کی بیشتر خودپسندی کی جڑیں دوسرے کے احساس میں پیوست ہوتی ہیں۔ آقا کی آقائیت غلاموں کی مرہونِ منت ہوتی ہے۔ غلام نہیں تو آقا بھی نہیں اور اس کی آقائیت بھی نہیں۔ ہم ایک ایسے صاحب سے واقف ہیں، جن کا تعلق ملک کے ایک دیہی علاقے سے ہے، لیکن وہ نقل مکانی کرکے کراچی میں آباد ہوگئے اور یہاں انہوں نے پے در پے بہت سی کامیابیاں حاصل کیں، لیکن ہم نے انہیں اپنی کامیابیوں پر کبھی مسرور ہوتے نہ دیکھا۔ ابتدا میں ہمارا خیال تھا کہ وہ جذبات کے اظہار کے قائل نہیں، لیکن رفتہ رفتہ ہم پر کھلا کہ وہ مسرور تو ہوتے ہیں، لیکن ان کی مسرت میں ایک گہری اداسی بھی موجود ہوتی ہے۔ ہم نے تجزیہ کیا تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ شہر میں ان کے عزیز بھی ہیں اور دوست احباب بھی، لیکن یہ لوگ عمرانی اصطلاح میں ان کے بنیادی یا ابتدائی گروہ سے تعلق نہیں رکھتے۔ ان کا بنیادی گروہ ان کے آبائی دیہی علاقے میں رہ گیا اور حالات کچھ ایسے تھے کہ وہ کبھی اپنے ابتدائی گروہ میں جاکر گھل مل نہ سکے اور نہ ہی اس گروہ میں سے کوئی ان کے قریب آکر رہ سکا۔ ہم نے یہ تجزیہ ایک دن ان کے سامنے رکھا تو وہ حیران ہوئے اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ایسا ہی ہے، لیکن انہیں اس بات کا اس طرح ادراک نہ تھا۔ انسانوں کی اکثریت سماجی نفسیات کے اسی دائرے میں زندگی بسر کرتی ہے۔
انسان کے لیے خود آگہی سے زیادہ اہم کیا ہوسکتا ہے، اور اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ دوسرے ہماری خود آگہی کا اہم حصہ ہیں۔ سقراط سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ تم نے دانش کہاں سے حاصل کی؟ اس نے جواب دیا کہ احمقوں سے۔ حقیقت یہی ہے کہ دوسرے ہمارے لیے ہمارے وجود کے انکشاف کا ذریعہ بنتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان انسانوں میں نہ سہی، انسانوں سے متعلق قصے کہانیوں اور ان کے متعلق واقعات میں گہری دلچسپی لیتا ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ انسان کے داخلی ارتقا کا انحصار کسی نہ کسی حد تک اس بات پر ہے کہ وہ دوسروں کے سلسلے میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔
رویّے سے مراد یہاں یہ ہے کہ کوئی انسان دوسروں کے لیے اپنے اندر کتنی گنجائش نکالتا ہے اور دوسروں کی قبولیت کے سلسلے میں اُس کی استعداد کا کیا عالم ہے۔ انسانوں کی قبولیت کے حوالے سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ کھدبد ہوتی ہے کہ شاید ان کے لیے اچھائی اور بُرائی اور گناہ و ثواب کے پیمانوں اور معیارات کو ساقط کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ پیمانے اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں دوسروں کو قبول کرنے کی خاصی فطری استعداد ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ دوسروں کے لیے درکار قبولیت کو شعوری کوشش ہی سے پیدا کرسکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دوسروں کو قبول کرنا ایک سخت روحانی، نفسیاتی اور جذباتی ریاضت ہے۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ وسعت کی خواہش بھی رکھتا ہے اور اس سے خوف بھی کھاتا ہے۔ فی زمانہ یہ خوف ہولناک حد تک بڑھ گیا ہے اور دوسروں کو قبول کرنے کی گھٹتی ہوئی استعداد اس کا ایک ثبوت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسانوں میں دوسرے انسانوں کی قربت اور انہیں قبول کرنے کی خواہش دم توڑ گئی ہے۔ یہ خواہش موجود ہے، لیکن اس کے محرکات بڑے خوفناک ہیں۔ ان میں سے تین محرکات اہمیت کے حامل ہیں:
1- دوسروں پر حکمرانی یا ان کے استیصال کی خواہش یا انہیں معمول بنالینے کی تمنا۔
2- دوسروں کو مقابلے، موازنے اور مسابقت کا ذریعے سمجھنے کی مریضانہ آرزو۔
3- سماجی، معاشی یا اسی قسم کے کسی بھی فائدے کے امکانات۔
فی زمانہ انسانوں کی قربت اور قبولیت کے ڈھونگ کی پشت پر یہی محرکات کام کرتے نظر آتے ہیں اور یہ بات بالکل عیاں ہے کہ ایسی قربتوں اور ایسی قبولیتوں کا انجام اور نتائج کیا ہوسکتے ہیں؟ کیا آپ سارتر کا مشہور زمانہ فقرہ بھول گئے؟؟