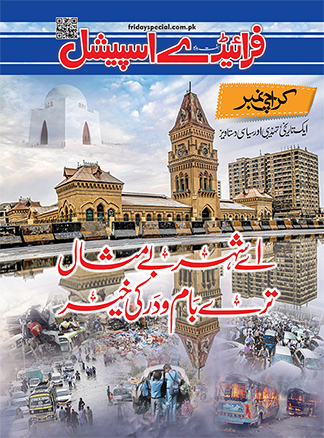تحریر:مائیکل ہیملٹن مورگن/ ترجمہ و تلخیص:ناصر فاروق
سمرقند، ازبکستان، 1417-1660ء… شاہراہِ ریشم پر، اندلس سے بہت دور مخالف سمت پر مسلم دنیا، سرحدوں سے بے نیاز، جہاں تیز ہواؤں کے جھکڑ چلتے تھے، یہ ریگستان کہلاتا تھا۔ یہاں تین عظیم الشان شاہکار مدرسے تکون حالت میں تعمیر کیے گئے تھے۔ مدرسوں کے منقش ستون، محرابیں اور در و دیوار ذوقِ جمال اور کمالِ فن ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اس دنیا کے لگتے ہی نہیں۔ جس زاویے سے دیکھیں، ماقبل تاریخ کے مقدس مقامات معلوم ہوتے ہیں، جیسے انگلینڈ کے Stonehenge اورگوئٹے مالا کے Tikal۔ یہ مدرسے فنِ تعمیرکے بے مثال نمونے ہیں۔
سن 1370ء، سمرقند… تیمورلنگ نے یہ شہر تعمیرکروایا تھا۔ اُس نے یہاں وہ وہ بنیادیں اٹھائیں، جن پر ایک دن وسطی ایشیا کے عظیم الشان فنی نمونے استوار ہونے تھے۔ منگولوں کے بعد، تیمورلنگ اس خطے میں طاقت ور ترین حکمران بن کر ابھرا تھا، اُس کی شان وشوکت اس شہر کی تعمیرات میں بھی بھرپور طور پر نمایاں ہوئی۔ پندرہویں صدی میں تیمور کے پوتے الغ بیگ نے شاہانہ روایت برقرار رکھتے ہوئے حکم جاری کیا کہ ریگستان میں عالیشان مدرسہ تعمیر کیا جائے۔ اس کا معمار قوام الدین شیرازی مقررہوا شیرازی نے گویا کسی ماورائی دنیا کی طلسماتی خوبصورتی زمین پر اتار دی تھی، ایک الف لیلوی تعمیری شاہکارتھا، کہ دیکھنے والا سحرزدہ ہوجائے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جنت کا کوئی باب کھل گیا ہو۔ یہ ایک مدرسہ تھا… تصورِعلم، تصورِ جمال، اور تصورِ تہذیب کا عمدہ عکاس۔
جب کوئی پہلی بار پُرشکوہ محراب کے سامنے پہنچتا، دونوں جانب ایستادہ منقش مینار آسمان کو سہار ا دیے سے محسوس ہوتے تھے۔ یہ درودیوار زمان ومکاں کی آفاقیت سے ہم آہنگ معلوم ہوتے تھے۔ یہ مدرسہ مابعدالطبیعاتی حقیقت سے ہم کلام محسوس ہوتا تھا۔ اگلی دوصدیوں میں ایسی مزید دو عمارتیں ساتھ ہی تکون کی شکل میں تعمیر کی گئیں، کہ اب گویا جیسے باہم ہم کلام ہوں۔ یہاں آنے والے اس تصورِ تعمیر پر تحیر آمیز نگاہ ڈالتے، اور داد دیے بغیر نہ رہ پاتے تھے۔ گو کہ یہ مدینہ ازہرہ اور الحمرا سے کوسوں دور تھے، مگر تصورِ تخلیق وجمال میں ایک ہی کائنات کے حصے معلوم ہوتے تھے۔ اندلسی عمارتوں کی مانند، ریگستان کے یہ مدرسے طرزِ تعمیر میں نزاکت اور نفاست کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ نیلے، زرد، اور سنہرے ٹائلوں کے جیومیٹرک نقش کائناتی رنگ لیے نظر آتے، جیسے شماریاتی اور فلکیاتی کلیوں کی آرائش کردی گئی ہو، ستاروں اور سیاروں کے عکس جیسے درو دیوار پر اتر آئے ہوں۔ ٹائلوں کے رنگ دلکش کیمیائی تاثر چھوڑتے ہیں۔ ریگستان مدرسے معماروں کی حیرت انگیز مہارت اور ذہانت کا فنی ثبوت ہیں۔ تاہم ان میں مدینہ ازہرہ اور الحمرا سی حساسیت اور جذباتیت نہیں ہے، بلکہ تیموری قوت وشوکت ہویدا ہے۔ یہ پتھروں میں چھپی اُن یادگاروں کی یاد دلاتے ہیں، جو ماضی ہوچکیں اورکبھی نہیں لوٹیں گی۔ ان کی بہت سی یکساں حالتیں مسلم میراث کی ترجمانی کرتی ہیں۔
ان مدرسوں کی عمارتیں قریب سے دیکھیں، اندرونی محرابوں میں تلا کاری عمدگی سے مقرنص کو سہارا دیتی نظر آتی ہے۔ یہ عمارتیں نہ صرف طلبہ کی تعلیم وتربیت اور رہائش کا اعلیٰ انتظام تھیں بلکہ یہ ایک جامع مسجد بھی تھی۔ تیمور اور اُس کے جانشینوں کے بہت بعد، یہ یادگاریں آج بھی پوری شان سے کھڑی ہیں۔ یہ آج بھی فن تعمیر کی بے مثل تحریک ظاہر کرتی ہیں۔ تیموری تعمیرات کوئی تاریخ گُم گَشتہ نہیں، بلکہ چھے صدیوں سے قائم زندہ جمالیاتی حقیقت ہیں۔
اصفہان، فارس، 1592ء… سولہویں اور سترہویں صدی میں یہاں ایک اولوالعزم اور باذوق سیاست دان شاہ عباس گزرا۔ سیاسی اکھاڑ پچھاڑکے بعد اُس نے اپنے والد کو تخت سے بے دخل کیا، اور زمامِ کار سنبھالی۔ اُس نے شاہراہِ ریشم سے تجارت اوردولت کا بہاؤ اصفہان کی جانب موڑ دیا۔ شاہ عباس برطانیہ کی مدد سے عثمان ترکوں اور دیگر یورپی نوآبادیاتی طاقتوں کا زورختم کرنا چاہتا تھا، تاکہ فارس کی علاقائی مرکزیت اورعظمت پھر سے قائم کرسکے۔ وہ جانتا تھا کہ فارس کبھی دنیا کا اہم تجارتی حب تھا۔ یہ علمی، فنی، اور مالی سرگرمیوں کا مرکز و محور تھا۔ مگر باہمی انتشار کے سبب اُسے وہ حیثیت اور پہچان نہ ملی تھی، جس کا یہ مستحق تھا۔ شاہ عباس نے عزم کیا کہ فارس کی شان و شوکت لوٹائے گا، فارس کے ٹکڑوں کو پھر سے متحد کرے گا۔ اُس نے ترکوں پر فتح حاصل کی، انھیں بہت پیچھے تک دھکیلا۔ اُس نے جارجیوں کو مغرب میں پسپا کیا۔ پرتگالیوں کو سمندرکے رستے بھاگنے پر مجبورکیا۔ اور یوں یورو ایشیائی تجارت کے دروازے اُس کے لیے کھل گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب شاہ عباس نے اصفہان کودارالحکومت بنانے کا فیصلہ کیا۔ گو کہ یہ شہر عہدِ سلجوق سے ہی حُسن کا شاہکار تھا، شاہ عباس نے اسے عظیم الشان بنادیا۔ اُس کی سرپرستی میں معماروں، منصوبہ سازوں، اور فنکاروں نے تعمیراتی پتھروں میں وہ بوقلمونی اور تنوع پیدا کیا، جو صدیوں تک خدائی طرزِ تخلیق کی گویا ترجمانی کرتا رہا۔ اس طرزِ تعمیر کے لازمی عناصرتھے: باغ، بڑا چبوترہ، ڈیوڑھی، گزرگاہ، گنبد، مینار، (کمرہ، خواب گاہ، چیمبر)، اور محراب۔ ان عناصرکے ساتھ ساتھ شاہ عباس اور دیگر منصوبہ ساز اصفہان کی میناکاری، استرکاری، اورگل کاری میں نئے رنگ بھررہے تھے، نئی مساجد اور محلات، نئے فنی نمونے سامنے لارہے تھے۔ انھوں نے اسے مسلم دنیا اور شاید بیشتر دنیا کا شاہکار ترین شہر بنادیا تھا۔
شاہ عباس کا یہ شہر ایک بہت وسیع چوک کے گرد تعمیرکیا گیا تھا۔ اسے شاہ یا امام اسکوائر پکارا جاتا تھا۔ یہ چوک 95,600 اسکوائر یارڈز، یعنی ماسکو کے ریڈ اسکوائر سے دُگنے رقبے پرپھیلا ہوا تھا۔ اپنے سنہرے دنوں میں یہ وسیع وعریض میدان شاہی چوگان (پولو)کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس شہر کے نوادرات میں مسجد شیخ لطف اللہ شامل ہے، اسے معمار محمد رضا بن استاد حسین اصفہانی نے تعمیر کیا تھا۔
دو میل کی وسعت پر پھیلا مستطیل چوک نیلے ٹائلوں کی طویل گزرگاہ کی مانند تھا، جہاں رنگا رنگ محلات، سرکاری دفاتر، اور رہائش گاہیں دور تک جاتی نظر آتی تھیں۔ مسجد شیخ لطف اللہ کی بابت برطانوی سفرنامہ نگار رابرٹ بائرن لکھتا ہے: ’’اتنی شاندار شے سے میرا پہلے کبھی سامنا نہیں ہوا۔ یہاں کا اندرونی طرزِ تعمیر اور نقش نگاری بے مثل ہے، میرے ذہن میں ویرسائی محل، یا شون برن کا پورسلین کمرہ، یا قصر دوک یا پطرس باسلیکاکا خیال آیا، مگر کوئی بھی اتنا پُرشکوہ نہیں ہے۔‘‘
اس شہرکا ایک اور تعمیری شاہکار عالی قاپو کا محل ہے، اس کی دیواروں پر درباری مصور رضا عباسی اور شاگردوں نے نقش نگاری کی، اعلیٰ فن پارے تخلیق کیے۔ رضا عباسی نے پھول، پرندے، درندے، فارسی فنی علامتیں ، اور روایتی نقوش ان دیواروں پر منتقل کیے۔ یہ پتھر، سونے، اورٹائل پر نقش گویا تصوراتی فارسی داستان گوئی ہے۔ یہاں کا تیسرا شاہکار مسجد امام ہے۔ اس کا پُرشکوہ چہرہ اورنیلے مینار مسجد شیخ لطف اللہ کے مقابل ایستادہ ہیں۔ اگرچہ یہ اپنی اصل میں فارسی ہیں، مگر یہاں اسلام کی دو جغرافیائی انتہاؤں کی گونج سنائی دیتی ہے، ایک اندلس اور دوسرا ریگستان۔ ریگستان کی مانند، اصفہان کی یادگاری عمارتوں میں آنکھوں کو چندھیا دینے والا سبز مائل نیلا ٹائل بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، نقش نگاری کی باریکیاں کائناتی پیچیدگی منعکس کررہی ہے۔ الحمرا کی طرح، یہاں کی عمارتوں میں مقرنصات معلق نظرآتے ہیں، جن پر عمدہ خوش نویسی کندہ کی گئی ہے۔
اصفہان میں نیلے پتھروں کا کام اس قدر عظیم الشان ہے کہ نگاہ ٹھیرتی نہیں۔ بلاشبہ، اصفہان انسانی تاریخ میں فنِ تعمیر کے شاہکار ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ مغربی یورپ نے مسلم فنِ تعمیر سے بہت کچھ اکتساب کیا۔ اسے فرانس، برطانیہ، اور آسٹریا کی شاہی عمارات میں اپنایا۔ بے تحاشا دولت و ثروت اور طاقت وقوت، شاہ فارس کا دربار فنی خصوصیات میں بے مثل تھا۔ پورے فارس کی مساجد اور اُن کے فلک بوس مینار اور دیگر فنی شاہکار خواہ محلات ہوں، قصبات کے مکانات ہوں یا باغات… یہاں کے باشندوں میں راحت کا احساس جاگزیں کرتے تھے۔ اصفہان کا یہ شاندار دور تاریخ کا وہ لمحہ تھا جسے کبھی پلٹ کر نہیں آنا تھا۔ یہ شاہ عباس کی طاقت اور تصورِ تخلیق وجمال کا بہترین آہنگ تھا۔
شاہ عباس کے بعد، جانشینوں میں جھگڑے چلتے رہے، ریاست کا پہیہ جام ہونے لگا۔ یورپیوں نے اپنی تجارتی گزرگاہیں بدل دیں۔ وہ اب سمندروں کے راستے تجارت کرنے لگے تھے۔ بڑے بڑے جہاز افریقا سے چکر لگاتے ہوئے بحرہند اور چین تک پہنچنے لگے۔ اصفہان اور وہ شہرجن کی معیشتیں شاہراہِ ریشم سے زندہ وتوانا تھیں، اب دم توڑ رہی تھیں۔
ان آخری وقتوں میں شاہ عباس نے ایک نظر امام اسکوائر پر ڈالی اور سوچا: ’’دیکھو، اے دیکھنے والو! اصفہان کی شان و شوکت دیکھو، اور فارسی قوم کی تخلیقی و فنی صلاحیتوں کا مشاہدہ کرو، کہ جب ان کی بصارتیں اور بصیرتیں اپنے کمال پر تھی، اور انھیں روشن اور دوررس تصورِ ترقی کی رہنمائی حاصل تھی۔‘‘
آج اصفہان کی یہ عمارتیں یونیسکو اقوام متحدہ کی جانب سے عالمی ورثہ قرار دی گئی ہیں۔
آگرہ، ہندوستان، 1631ء… ایک مغل بادشاہ تھا، شہاب الدین محمد شاہ جہاں اُس کا نام تھا۔ اُس کی کئی بیویاں تھیں، مگر ممتاز اُس کے دل سے بہت قریب تھی۔ کم سنی میں ہی ان کی شادی ہوگئی تھی۔ یوں تقریباً ساری زندگی ساتھ ہی گزری۔ ممتاز سے شاہ جہاں کے چودہ بچے ہوئے۔ وہ جنگوں تک میں شاہ جہاں کی ہمرکاب رہی۔ وہ اس قدر یک جان دو قالب بن کر رہے کہ جدائی کا تصور ممکن نہ رہا۔ اس بے مثل محبت کے علاوہ شاہ جہاں مغل بادشاہوں میں سب سے خوش نصیب تھا۔ وہ ایک ایسی سلطنت کا فرماں روا تھا، جو اپنے اندر ایک دنیا تھی۔ سترہویں صدی کے ہندوستان کی دولت روئے زمین پرکسی بھی دوسری ریاست سے زیادہ تھی، یہاں تک کہ یورپ کی ابھرتی ہوئی استعماری قوتیں بھی مالی طورپر کمزور تھیں، اور ہندوستان پر للچائی ہوئی نظریں جمائے ہوئے تھیں۔
یہ ملک… گوکہ یہاں مسلمان حکمران تھے… مختلف قوموں، مذاہب، زبانوں، اور ثقافتوں کی سرزمین تھی۔ مساجد کے امام عربی بولتے اور لکھتے تھے۔ مغل جو دراصل وسطی ایشیائی تھے، فارسی طرزِ زندگی اپنا چکے تھے، اب قدیم ہندوستان کی فتح کے بعد علاقائی تعلق کا دائرہ مکمل کررہے تھے۔ شاہ جہاں کے آباء میں ازبکستان کا جلال الدین بابر وہ پہلا حکمران تھا جس نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی، اور اکبر اعظم جسے ایک دن ہندوستان کا مثالی حکمران قرار دیا گیا۔ شاہ جہاں میں نہ اکبر کی سی وسعتِ نظر تھی اور نہ بابر کی سی جرأت وبہادری، مگر وہ عظیم معمار بن کر تاریخ میں انمٹ ہوگیا۔ اُس نے دِلّی کا لال قلعہ بنوایا، جو مغل طرز تعمیرکا عکاس ہے۔ اُس نے شاندار محلات اور باغات بنوائے۔
سن 1631ء… شاہ جہاں حالتِ جنگ میں تھا، ممتاز حاملہ تھی، ہمرکاب بھی تھی۔ منع کرنے کے باوجود وہ ساتھ تھی۔ اس سفر میں شہزادی گوہر بیگم کی پیدائش ہوئی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک انداز میں ہوا۔ مگر مقدر نے ان لمحات میں ممتاز کی موت کا فیصلہ دے دیا۔ یہ دنیا کی دولت مند ترین ریاست کے حکمران کے لیے ناقابلِ تلافی نقصان تھا، گویا وہ خود سے جدا ہوگیا تھا، دل جیسے بند ہوگیا تھا، ممتاز کے بغیر زندگی، زندگی نہ تھی۔ شاہ جہاں گرد و پیش سے بے خبر ہوچکا تھا، حواس جواب دے چکے تھے۔ عالیشان محلات، ہزاروں ہاتھیوں کے لشکر، ہیرے، موتی، جواہرات کی بھرمار، بے شمار عوام اور اُن کی دعائیں اور محبتیں، کسی شے کا کوئی وجود نہ رہا تھا۔ وہ مرجانا چاہتا تھا۔ مگر زندگی آگے بڑھ گئی۔
مغل درباری مؤرخ عبدالحامد لاہوری نے لکھا کہ ’’ممتاز کی موت نے شاہ جہاں کا پہاڑ جیسا صبر وضبط ڈھا دیا تھا، شاہ جہاں کی داڑھی راتوں رات سفید پڑگئی تھی، ایک ہفتے تک وہ لوگوں کے سامنے نہ آیا‘‘۔ سترہویں صدی کے سفرنامہ نگارFrancois Bernier نے لکھا کہ ’’شاہ جہاں کی ممتاز سے محبت کا یہ عالم تھا کہ گویا اُس کے پیچھے قبر ہی میں جاپہنچے گا۔‘‘
شاہ جہاں نے پھر ممتاز کی یادگار تعمیرکرنے کا ارادہ کیا، ایسی یادگارکہ جو دیکھنے والوں کے لیے ایک یادگار موقع بن جائے۔ ایسی یادگار کہ نگاہ ٹھیر جائے، سانس بے ربط ہوجائے، خیال معطل ہوجائے، اور تصورِ محبت مستحکم ہوجائے۔
احکامات جاری ہوئے، ہدایات دی گئیں، تجاویز سامنے آئیں، اور پھرمعماروں، خوش نویسوں، اور مزدوروں کی پوری فوج جُت گئی۔ پورے ہندوستان سے، فارس سے، ترکی سے بیس ہزار کاریگر آگرہ میں جمع ہوئے۔ انھیں کہا گیا کہ عظیم ترین یادگار قائم کرنی ہے، جو اس عظیم محبت کے شایانِ شان ہو۔ گو لاکھوں شاہی دستاویزات ضائع کردی گئیں، تاہم مؤرخین کہتے ہیں کہ معماروں کی حتمی ٹیم میں استاد احمد لاہوری اور خود شاہ جہاں شامل تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے خود منصوبہ بندی کی،کئی تبدیلیاں کیں، معماروں کے ساتھ مشاورت اور تبادلہ خیال بھی کیا۔
شاہ جہاں کی دلی آرزو اور معماروں کی تخلیقی صلاحیتوں نے گویا آسمان سے ایک محل دریائے جمنا کے کنارے اتار دیا، جیسے فراق اور ہجر میں رنگی کوئی غزل سنگِ مرمر پر لکھ دی گئی ہو۔
ہاتھیوں کے لشکر راجستھان سے ٹنوں سنگِ مرمر آگرہ پہنچاتے رہے۔ پنجاب سے جاسپر، سرخ زرد نگینے آگرہ لاتے رہے۔ یہ قرآنی آیات کی خوشی نویسی کے لیے استعمال کی گئی۔ چین سے قیمتی پتھر جیڈ اور بلور منگوائے گئے، سجاوٹوں اور روشنیوں کا انتظام کیا گیا۔ تبت سے فیروزہ لایا گیا۔ لاجورد شوخ نیلا نگینہ افغانستان سے درآمد کیا گیا۔ سری لنکا سے نیلم لایا گیا۔ سنگِ یمانی عرب سے آگرہ پہنچایا گیا۔ اٹھائیس اقسام کے سنگِ مرمر اس محل کی تعمیر میں استعمال کیے گئے۔ بائیس سال کی مسلسل محنت اور جانفشانی سے یہ شاہکار تیار ہوا۔ پچاس کروڑ ڈالر کی خطیر رقم اس محل پرخرچ کی گئی۔ اس یادگار کا نام تاج محل رکھاگیا۔ اس کے چاروں کونوں پر سنگِ مرمر کے مینار اٹھائے گئے۔ وسط میں سنگِ مرمر کا ایک سفید گنبد بنوایا گیا۔ چوٹی پر ایک اسلامی چاند لگوایا گیا۔
تاج محل کی تکمیل کے پانچ سال بعد، سن 1653ء میں شاہ جہاں کو بیٹے اورنگزیب نے اقتدار سے بے دخل کردیا۔ اورنگزیب نے شاہانہ طرزِ حکومت اور معاملات کو پھر سے زمین پر اتار دیا۔ شاہ جہاں نے زندگی کے آخری ایام نظربندی میں بسر کیے، وہ جھروکوں سے تاج محل کا دیدار کیا کرتا تھا۔ جب وہ مرا، تو اورنگزیب نے بڑی تکریم سے ممتاز کے برابر میں شاہ جہاں کی تدفین کروائی۔
شاہ جہاں نے ارادہ کیا تھا کہ تاج محل کے سامنے سیاہ سنگِ مرمر کا ایک محل اپنے لیے تعمیر کروائے، جوممتاز سے جدائی کے برسوں کی علامتی یادگار بن جائے۔ مگر یہ ہو نہ سکا۔ تاج محل کے گنبد کے عین نیچے ممتاز کی قبر تھی، شاہ جہاں کی قبر اُس کے برابر میں وسط سے ذرا ہٹ کر بنوائی گئی۔
پھر اس جگہ پر مشکل زمانے گزرے۔ مغلوں پر زوال آگیا۔ لٹیرے آگرہ پہنچ گئے۔ جب برطانیہ نے ہندوستان پر حملہ اور قبضہ کیا، برطانویوں اور اُن کے مقامی گماشتوں نے تاج محل کے قیمتی پتھر چُرا لیے۔ بعد میں ایک برطانوی وائسرائے نے حکم دیا کہ محل کی خوبصورتی بحال کی جائے۔