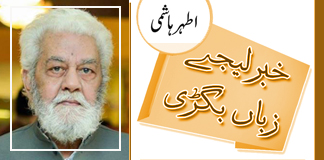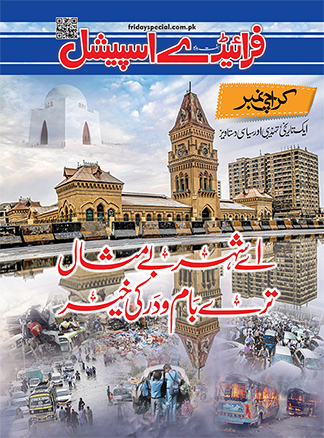امریکا سے محسن نقوی مزید لکھتےہیں “اردو گرامر کی ابتدائی کتابوں میں ایک اہم نام جان گلکرسٹ کی ’قواعد زبان اردو‘ کا ہے جو بنیادی طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز ملازمین کو مقامی زبان سے آشنا کرانے کے لیے لکھی گئی تھی۔ متن انگریزی میں تھا اور اردو کے اسما و افعال کا تجزیہ لاطینی، یونانی اور انگریزی اصولوں کے مطابق کیا گیا تھا۔
انیسویں صدی کے دوران میں مغربی انداز میں لکھی ہوئی گرامریں اتنی بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں کہ ان کے سرسری تذکرے کے لیے بھی ایک پوری کتاب درکار ہو گی، البتہ جان ٹی پلیٹس کی گرامر ان میں نمایاں ترین مقام رکھتی ہے۔ اس کی تمام عمارت بھی لاطینی بنیادوں پر استوار کی گئی ہے، لیکن کتاب چونکہ انگریزی میں ہے اس لیے لاطینی، ڈچ، پرتگیزی اور جرمن زبان میں لکھے گئے متون کے مقابل اہلِ ہند کے لیے زیادہ مفید رہی اور 1874ء میں شائع ہونے والی یہ کتاب آج ڈیڑھ صدی گزرنے کے بعد بھی مقامی اہلِ قواعد کے لیے اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے۔
خود اہلِ ہند میں انشا اللہ خان انشا پہلے شخص تھے جنہوں نے اردو زبان کے قواعدی ڈھانچے کا مطالعہ کیا اور ’دریائے لطافت‘ کی شکل میں ایک سدا بہار تحفہ اردو کو دیا۔
انیسویں صدی میں چھپنے والی اردو گرامر کی تین کتابوں کا ذکر یہاں بے جا نہ ہو گا۔
1 ۔ مولوی احمد علی دہلوی کی فیض کا چشمہ: 1825ء
2 ۔ سرسید احمد خان کا رسالہ ’اردو صرف و نحو‘:1842ء
3 ۔ مولوی امام بخش صہبائی کی ’اردو صرف و نحو‘: 1849ء ”
عربی کے بعض تعظیمی کلمات اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگوں پر ان کا تلفظ واضح نہیں ہوتا، چنانچہ جیسا چاہے پڑھ لیتے یا بول جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کلمہ ’’قدس سرہ‘‘ ہے۔ ہم بربنائے جہالت ’قدس‘ کو القدس کی طرح (بروزن بغض) اور ’سرہ‘ کو رفاہ کے وزن پر پڑھتے اور بولتے رہے۔ ایک پڑھے لکھے شخص کے سامنے بھی یہی کہہ دیا۔ لیکن وہ ہماری طرح نہیں، صاحبِ ظرف تھا۔ صحیح تلفظ دہرا کر تصحیح کردی۔ مناسب طریقہ یہی ہے کہ کوئی غلط لفظ بولے یا تلفظ میں گڑبڑ کرے تو صحیح تلفظ ادا کردیا جائے۔ لیکن کبھی کبھی یہ نسخہ کام نہیں آتا اور دوسرا شخص تصحیح قبول کرنے کے بجائے اپنے کہے پر مُصر رہتا اور شاید دوسرے کو غلط سمجھتا رہتا ہے۔
بات ہورہی تھی قدس سرہٗ کی۔ اس کا تلفظ ’قَد۔دَس‘ ہے، اور ’سِرّہٗ‘ کا پہلا حرف بالکسر، ’ر‘ پر تشدید اور ’ہ‘ پر الٹا پیش۔ قَدس اللہ سِرّہٗ بھی کہتے ہیں۔ (اللہ تعالیٰ اس کے بھید پاک کرے)
پچھلے کالم (22 تا 28 فروری) میں ہم نے انواراللغات پر بھروسا کرتے ہوئے ایک شعر دیا تھا جس کا دوسرا مصرع تھا ’’ایک دن مہر نہ ذرا کے برابر چمکا‘‘۔ ایک اختلافی نوٹ دے دیا تھا کہ ’’ذرا کے برابر‘‘ کا مطلب شاعر ہی کو معلوم ہوگا۔ اس سے بچت ہوگئی۔ معروف ادیب و شاعر اور علم عروض کے ماہر جناب عزیز جبران انصاری نے توجہ دلائی ہے کہ یہ ’’ذرّہ کے برابر‘‘ ہوگا، ورنہ تو ذرا سے وزن بھی ذر ا سا رہ جائے گا، اور مطلب ہے کہ سورج ذرّے کے برابر بھی نہ چمکا۔ اردو لغات میں کتابت کی ایسی غلطیاں عام ہیں اور اسی لغت میں ’ناصبور‘ کو ناسبور لکھا ہے۔ طالبانِ علم اسی کو سند سمجھ لیں گے۔ عزیز جبران انصاری کا شکریہ۔
ا سا رہ جائے گا، اور مطلب ہے کہ سورج ذرّے کے برابر بھی نہ چمکا۔ اردو لغات میں کتابت کی ایسی غلطیاں عام ہیں اور اسی لغت میں ’ناصبور‘ کو ناسبور لکھا ہے۔ طالبانِ علم اسی کو سند سمجھ لیں گے۔ عزیز جبران انصاری کا شکریہ۔
بہت پڑھے لوگوں کی جماعت جس کے بانی کے علم اور ادب کی دھوم ہے، اس جماعت کے سیکریٹری اطلاعات برائے کراچی کا ایک مراسلہ سامنے ہے جو شاہکار ہے۔ ایک جملہ ہے ’’سوشلزم کی مداح سرائی‘‘۔ کاش کسی سے پوچھ لیا ہوتا کہ ’مداح سرائی‘ اور ’مدح سرائی‘ میں کیا فرق ہے۔ مداح ہی لکھنا تھا تو سرائی نہ لکھتے۔ لیکن مدح اور مداح کا مفہوم مختلف ہے۔ ایک اور جملہ دیکھیے ’’ہمارے حلقے اثر میں‘‘۔ ارے بھائی ’حلقۂ اثر‘ لکھنے میں کیا قباحت تھی۔ اگر اس میں سے ’اثر‘ نکال دیتے تو بھی بات بن جاتی۔ اس مراسلے کے آخر میں ایک نوٹ ہے اور یہ نوٹ چہرۂ شاہی نہیں بلکہ، خیر جانے دیجیے۔ لکھتے ہیں ’’خط کی کاپی ساتھ منسلک ہے‘‘۔ کیا عسکری اردو ہے۔ جی خوش ہوگیا۔ ’’ہمیں ان سے توقع تھی خستگی کی داد پانے کی‘‘۔
’علاوہ‘ اور ’سوا‘ کی الجھن دور نہیں ہوئی۔ انتہائی معتبر جریدے عالمی ترجمان القرآن شمارہ فروری میں حسن البنا شہید کا ایک بہت وقیع مضمون بعنوان ’’اسلام کی نظر میں عورت!‘‘ شائع ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ سید حامد علی نے کیا ہے۔ اس میں ایک جملہ ہے ’’نکاح کی شکل کے علاوہ وہ دونوں کو ایک دوسرے سے دور دور رکھتا ہے‘‘۔ ہمارے خیال میں یہاں علاوہ کی جگہ ’سوا‘ ہونا چاہیے، اور اگریہ سہو ہے تو ظاہر ہے کہ ترجمہ کرنے والے کا ہے یا مدیران جریدہ کا صرفِ نظر۔ لیکن ہم الجھن میں پڑ گئے ہیں۔
کامیابیاں کی نفی ناکامیابیاں شاید صحیح ہو، لیکن ناکامیاں بہتر ہے۔ کامیابی کا متضاد ناکامی ہے، نہ کہ ناکامیابی۔ ’کبھی بھی‘ کا ایک ساتھ استعمال غیر فصیح اور بھونڈا پن ہے۔ پروفیسر آسی ضیائی (مرحوم) ’’درست اردو‘‘ میں لکھتے ہیں کہ ’کبھی‘ اور ’کسی‘ کے ساتھ ’بھی‘ لانا غیر فصیح ہے۔ ’بھی‘ کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔ عوام کی بول چال میں ’کبھی بھی‘ تو آتا ہے اور بعض ادیب بھی لکھتے ہیں، لیکن اس کے خلافِ فصاحت ہونے پر فصحا کا اتفاق ہے۔ اس پر ایک شعر استاد قمر جلالوی کا یاد آگیا۔ اب تک کوئی شعر آیا بھی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں:
کبھی کہا نہ کسی سے ترے فسانے کو
نجانے کیسے خبر لگ گئی زمانے کو
جس دور میں یہ شعر کہا گیا تھا اُس وقت تک سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ کہیں پالنے میں ہوں گے، ٹی وی چینلز بھی اتنے متحرک نہیں تھے۔ چنانچہ استاد کی حیرت بجا تھی کہ زمانے کو کیسے خبر لگ گئی!
جہاں تک ’کسی‘ کا تعلق ہے مثلاً یہ جملہ کہ ’’میں نے یہ بات کسی بھی شخص سے نہ کہی‘‘۔ تو اردو میں کسی بھی تو نہ لکھا جاتا ہے اور نہ بولا۔ ہندی تحریر میں اس کا رواج عام ہے، مگر بولتے وہ بھی نہیں۔ اگر زور دینے کے لیے کسی کے ساتھ ’بھی‘ لانا ضروری سمجھا جائے تو ان دونوں کے بیچ میں کم از کم دو لفظ ہونے چاہییں، ایک تو کسی کا موصوف اور دوسرا حرفِ جار۔ چنانچہ جملہ اس طرح صحیح ہوگا ’’میں نے یہ بات کسی شخص سے بھی نہیں کی‘‘۔ یہاں کسی کے موصوف ’شخص‘ اور حرفِ جار ’سے‘ کے بعد ’بھی‘ آیا ہے۔
قواعد کی رو سے تو ’قریباً‘ کا استعمال درست ہے، مگر اس کو بالعموم علماء دین کی زبان و قلم ہی پر آتے دیکھا گیا ہے، عام اہلِ زبان نہ بولتے ہیں نہ لکھتے ہیں۔ اس کی جگہ ’تقریباً‘ لانا بہتر ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مجھے قریباً قریباً دس ہزار کا منافع ہوا تو ایسے موقع پر ’قریب قریب‘ لکھنا، کہنا چاہیے۔ اردو میں ’دل کرنا‘ بھی کوئی روزمرہ نہیں۔ اس کی جگہ ’دل چاہنا‘ یا ’جی چاہنا‘ لانا چاہیے، مثلاً ’’میرا بڑا دل کرتا ہے کہ آپ سے ملنے آئوں‘‘۔ اس جملے میں ’’بڑا دل کرتا ہے‘‘ کے بجائے ’’دل (جی) چاہتا ہے‘‘ ٹھیک ہے۔ ویسے جو آپ کا دل چاہے۔