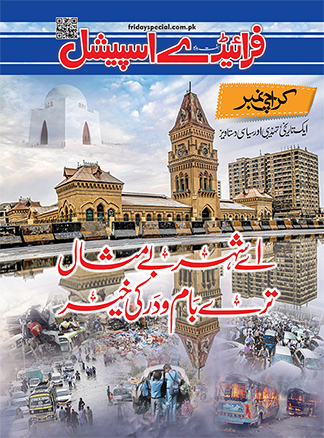وہ تینوں بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، اس لیے ہم بچوں میں ’’چھوٹے ابا‘‘ کہلاتے تھے۔ قد میں تھے بھی کم، چھوٹے سے… لیکن سمجھ بوجھ میں، محنت و منصوبہ بندی میں، یہاں تک کہ حقیقت پسندی اور حقیقت پسندانہ فیصلوں میں اپنے دونوں بڑے بھائیوں یعنی ابا اور ابی جان سے کہیں زیادہ بڑھے ہوئے تھے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو انہیں میڈیکل کالج میں ڈاکٹری کی تعلیم پاتے ہوئے دیکھا۔ روزانہ صبح کو ڈاکٹروں والا سفید ایپرن پہنے، ایک ہاتھ میں ڈاکٹری آلہ اور دوسرے ہاتھ میں انسانی ہڈی لیے سیڑھیوں سے اُترتے۔ ناشتا ان کا تیار ہوتا۔ ہاف فرائی انڈہ اور موری روٹی (پراٹھا) کھا کر اور چائے کا ایک کپ پی کر اپنی چمچماتی سائیکل باہر نکالتے اور اس پر سوار ہوکر کالج روانہ ہوجاتے۔ یہی ان کا روزانہ کا معمول تھا۔ واپسی پہ وہ سائیکل اپنی جگہ پہ کھڑی کرکے میری چچی (جنہیں ہم ’’امی‘‘ پکارتے تھے کہ چچی بھی تھیں اور خالہ بھی) کے کمرے میں چلے جاتے۔ بچیاں انہیں دیکھ کے بھاگ کے بستر کے کونوں میں چلی جاتیں کیوں کہ انہیں معلوم تھا کہ اب چھوٹے ابا انہیں قریب بلاکر خوب پیار کریں گے اور پھر اپنے کمرے میں چلے جائیں گے۔ کمرہ ان کا اوپری منزل پہ تھا۔ میڈیکل کی موٹی موٹی کتابیں، جو میز پر رکھے شیلف پر سجی ہوتیں۔ میز کے ساتھ دھری کرسی کے دائیں جانب کھڑکی تھی جو باہر کی طرف کھلتی تھی اور جس سے باہر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ ہرے پانیوں سے بھرا تالاب، پھر میدان جس میں ہم بچے سرِشام جمع ہوکر ٹینس کی گیند سے کھیلتے تھے۔ میدان سے متصل ایک پتلی سی مگر پختہ سڑک، اور
سڑک کے کنارے پر قطار سے بنے ہوئے مکانات جن میں زیادہ تر بنگالی رہتے تھے، اردو بولنے والوں یا بہاریوں کے لیے میدان کے مشرق کی جانب قدیم طرز کی ایک بہت بڑی عمارت جس کی دیواریں بھی شکستہ اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، یہ عمارت ’’بہاری بلڈنگ‘‘ اپنے مکینوں کی وجہ سے کہلاتی تھی۔ اس میں اندازاً کچھ نہیں تو بیس پچیس خاندان آباد تھے۔ غالباً یہ متروکہ املاک تھی جس کو بہار سے فساد زدہ لٹے پٹے آنے والے مہاجرین نے اپنے سرچھپانے کا ٹھکانہ بنالیا تھا۔ چھوٹے ابا کے کمرے کی کھڑی سے یہ سارا منظر ایسے دکھائی دیتا تھا جیسے کوئی پینٹنگ جہازی سائز دیوار سے لٹکی ہو۔ چھوٹے ابا کو اکثر دیکھا تھا کہ اس کھڑکی پہ کھڑے ہو کے باہر دیکھتے رہتے تھے۔ میرا بھی جی چاہتا تھا کہ اس کھڑکی کے منظر سے لطف اُٹھائوں، لیکن اُن کے کمرے میں جانے کی ہمت کب پڑتی تھی! ایسا نہیں تھا کہ ہمیں اندر جانے سے منع کیا گیا تھا یا کوئی پابندی تھی… نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آج کل کے برعکس اُس زمانے کی تہذیب و معاشرت کی قدریں کچھ ایسی تھیں کہ جو ہمارے اندر رچی بسی تھیں اور ان میں سب سے بڑی قدر تھی بڑوں کا احترام، ان کی عزت۔ بڑے بے تکلف کرنا بھی چاہیں تو اپنی حدود سے آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ چناں چہ میں جب بھی چھوٹے ابا کے کمرے میں گیا، اُن کے بلانے پر ہی گیا۔ اور وہ بلاتے اُس وقت تھے جب قیلولے کی غرض سے بستر پہ دراز ہوتے تھے۔ انہیں پائوں دَبوانے کی عادت تھی۔ یہ بھی اُس زمانے کے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ بچوں سے خدمت کا کام لیا کرتے تھے۔ اب سوچتا ہوں تو اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ بڑوں کی خدمت سے بچوں میں خدمت کی عادت پڑتی ہے۔ خدمت بھی عادت ہی کا نام ہے۔ عادت نہ ہو تو ذرا سا کام دوسرے کا کرکے ہم یوں سمجھتے ہیں جیسے کوئی احسان کردیا۔ اور جب احسان کیا اور اس احسان کا احساس بھی اندر پیدا ہوگیا تو اس کے عوض اور بدلے کی طلب بھی اندر پیدا ہوجاتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم بچوں نے اپنے دادا، اپنے ابا اور چھوٹے ابا کے پائوں خوب دابے۔ دونوں بھائیوں کی عادت تھی کہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ اب بس کرو۔ یہ ذمے داری ہماری تھی کہ خود اندازہ کریں کہ اگر سوگئے ہیں، نیند آگئی ہے تو چپکے سے اُتر کر بستر سے دبے پائوں بھاگ لیں۔ بات نکل ہی آئی ہے تو ایک واقعہ سنادوں جس سے اندازہ ہوسکے گا کہ بڑوں کا بے نام سا خوف یا احترام کس طرح ہم بچوں میں تھا۔ ایک دوپہر میں آنگن میں ایستادہ بیری کے درخت پہ چڑھ کر بیر توڑتا جاتا تھا اور کھاتا جاتا تھا کہ اچانک دروازے پہ سائیکل کی گھنٹی بجی۔ اوپر سے جو دیکھا تو ابی جان سائیکل کا ہینڈل تھامے کھڑے تھے۔ اپنی تو روح فنا ہوگئی، اس اندیشے سے کہ ان کے سامنے اُترا تو کہیں ڈانٹ نہ پڑے، اوپر ہی بیری کے پتوں میں چھپ کے بیٹھا رہا۔ ابی آئے، نہائے دھوئے، آنگن ہی کے سائے میں چوکی پہ بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھایا اور پھر سائیکل اٹھا کے رخصت ہوئے۔ اتنی دیر تک میں تقریباً دم سادھے درخت کے تنے پر بیٹھا رہا۔ نیچے اترنے کی ہمت ہی نہ پڑی۔ چھوٹے ابا سے ایسا کوئی خوف یا ڈر ڈانٹ ڈپٹ کا کبھی نہ ہوا، اس لیے کہ اُن کی طبیعت میں بہت نرمی اور ملائمت تھی۔ کبھی بلند آواز سے بھی بات نہ کرتے تھے۔ بہت خوش مزاج تھے، ہنستے تھے تو خوب ہنستے تھے، دیر تک ہنستے رہتے تھے۔ ان کے کمرے میں خوب بڑے سائز کا ایک ریڈیو تھا۔ ٹیلی وژن تو تب تک ملک میں آیا ہی نہ تھا۔ ریڈیو ہی انسانی ایجاد کا ایک معجزہ نظر آتا تھا۔ میں تو ریڈیو سنتے ہوئے اپنی معصومیت یا لاعلمی میں گمان کرتا تھا کہ اس ڈبے کے اندر چھوٹے چھوٹے لوگ بند کردیے گئے ہیں جو گاتے ہیں، خبریں پڑھتے اور ڈرامے کرتے ہیں۔ بہت جی کرتا تھا کہ کسی دن جب چھوٹے ابا نہ ہوں، اس ڈبے کو کھول کر ان لوگوں کو باہر نکالوں اور اتنے اچھے اچھے پروگرام کرنے پر ان کا شکریہ ادا کروں۔ بچوں کا ایک خصوصی پروگرام بھی آتا تھا۔ چھوٹے ابا پروگرام شروع ہونے پر ہمیں آواز دے کے بلالیتے تھے، اور ہم گھر کے سارے بچے ریڈیو کے گرد جمع ہو کے مُنّی باجی کا پروگرام نہایت شوق سے سنتے تھے۔ منی باجی اپنی معصوم بھولی بھالی آواز میں خطوں کا جواب دیتی تھیں اور بہت پیاری پیاری باتیں پیارے انداز میں بچوں سے کیا کرتی تھیں۔ (بعد میں کراچی ریڈیو اسٹیشن میں جب آنا جانا ہوا تو میں نے منی باجی کو نہایت اشتیاق سے دیکھا، وہ واقعی منی سی تھیں)۔ مجھے یاد ہے 1965ء کی جنگ میں اسی ریڈیو سے ہم نے شکیل احمد نیوز ریڈر کی بھاری گونج دار آواز میں خبریں، اور مادام نورجہاں اور مہدی حسن سے پُرسوز ملّی نغمے سنے جو روح میں ایک وجد پیدا کردیتے تھے۔ چھوٹے ابا کی طبیعت میں جیسا کہ عرض کیا، بہت نرمی اور رقت تھی۔ البتہ ایک واقعہ ایسا ہے جس میں ہم بچوں نے اُن کے غصے بلکہ جلال کا مشاہدہ کیا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ہمارے دو منزلہ مکان کے عقب میں غریب ہندوئوں کے جھونپڑے تھے۔ ان کی عورتیں گھروں میں صفائی ستھرائی، اور مرد مختلف قسم کی محنت مزدوری کرتے تھے۔ یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ میرے بڑے بھائی ایک شام میدان میں سائیکل سے نکلی ہوئی گھنٹی کو کھلونا بنا کے اس سے کھیل رہے تھے کہ ایک ہندو اسی جھونپڑے کا ادھر سے گزرتے ہوئے رکا، اس نے بھائی کی گھنٹی کو غور سے دیکھا، دیکھتا رہا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر بھائی کے ہاتھ سے وہ گھنٹی چھین لی یہ کہہ کر کہ یہ میری ہے، تُو نے اسے کہاں سے چرایا ہے؟ یہ کہہ کر وہ بنگالی میں بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ بھائی ہمارے روتے ہوئے گھر آئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ رات میں چھوٹے ابا آئے، انہیں جب یہ قصہ معلوم ہوا تو ان کے چہرے کی رنگت ہی بدل گئی۔ ساتھ کی کوٹھری میں گئے جہاں سائیکلوں کی بہت سی ناکارہ گھنٹیاں پڑی تھیں۔ ابا اور ابی جان کا کاروبار ہی کتابوں کی فروخت اور اخباروں کی شہر بھر میں ترسیل کا تھا۔ اس مقصد کے لیے دس بارہ ہاکر ملازم تھے جنہیں ترسیلِ اخبار کے لیے سائیکلیں دے دی گئی تھیں، اور ان سائیکلوں کی جو گھنٹیاں ناکارہ ہوجاتی تھیں انہیں اسی کوٹھری میں ڈال دیا جاتا تھا۔ چھوٹے ابا نے ایک تھیلے میں یہ ساری گھنٹیاں اکٹھی کیں اور پیچھے جھونپڑے میں گئے۔ اور جس ہندو نے بھائی پر گھنٹی چرانے کا الزام لگایا تھا اُسے آواز دے کر باہر بلایا، جب وہ باہر کچے صحن میں آیا تو اُس کے سامنے تھیلا اُلٹ دیا۔ گھنٹیاں ڈھیر ساری اِدھر اُدھر لڑھک گئیں۔ چھوٹے ابا نے قدرے درشت اور بلند آواز میں بہ زبانِ بنگالی کہا:’’اس میں کون کون سی گھنٹیاں تیری ہیں، پہچان کر اُٹھالے‘‘۔
اب وہ بنگالی ہندو، کاٹو تو بدن میں اُس کے لہو نہیں۔ ہم سارے بچے اوپری منزل کی کھڑکی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ دل بھی ہمارے بری طرح دھڑک رہے تھے کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے؟ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ اس شخص کی سائیکل کی گھنٹی کسی نے چرا لی تھی، وہ تلاش میں تھا، بھائی کو گھنٹی سے کھیلتے دیکھ کر اُسے شبہ ہوا جو جلد ہی اس یقین میں بدل گیا کہ ہو نہ ہو اسی بچے نے گھنٹی چرائی ہے ورنہ یہ گھنٹی اس کے پاس کہاں سے آئی؟ مجھے یاد ہے چھوٹے ابا نے اس سے زیادہ کچھ نہ کہا، اس لیے کہ الزام لگانے والے کو اندازہ ہوگیا کہ اُس نے بے بنیاد الزام تراشی کرکے کیا حماقت کی ہے۔
چھوٹے ابا کے اس قدر غصے یا جلال کا اصلی سبب کیا تھا؟ تب تو یہ بات کم سنی اور کم شعوری کی وجہ سے سمجھ میں نہ آسکی تھی، لیکن بعد میں یہ بات کھلی کہ چھوٹے ابا کے غصے اور اشتعال کی وجہ فقط یہ تھی کہ الزام لگانے والا ہندو تھا۔ ہندوئوں سے بیزاری کی وجہ وہ زخم تھا جو بچپن میں، 1946ء میں بہار کے گائوں ہرلہ میں مسلم کُش فسادات میں ہندوئوں کے نیزے سے اُن کے سر پہ لگا تھا۔ ہندو فسادی حملہ آور تو وار کرکے انہیں مُردہ جان کر انہیں ان کی ماں کی گود میں چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن قدرت کو زخمی ماں بیٹے کی زندگی منظور تھی، اس لیے دونوں بچ گئے۔ جب وہ اس ہندو کے سامنے گھنٹیوں کا تھیلا اُلٹ کر کھڑے غصہ ضبط کرنے کی وجہ سے بری طرح کانپ رہے تھے، ہاں وہ زخم تب بھی ان کے سر پہ چمک رہا تھا۔ کبھی کبھار چھوٹے ابا کے کہنے پر میں اُن کے سر پہ تیل کی مالش کرتا تھا جب وہ تکیے کے نیچے تولیہ بچھاکر آنکھیں موندے لیٹے ہوتے تھے تو میری انگلیاں اس کئی انچ گہرے زخم کے دھنسے ہوئے نشان کو ٹٹولتی رہ جاتی تھیں۔ میں نے ان کی زبان سے کبھی اس سانحے کی بابت کچھ نہیں سنا۔ البتہ پچھلے برس وہ امریکہ سے آئے تو کیمپس میں واقع میرے مکان کے لان پہ جب موسم سرما کا سورج آسمان پہ چمک رہا تھا، اور ایسے میں ویسے بھی بھولے بسرے ماضی کو یاد کرنا اچھا لگتا تھا، پرانی باتیں نکل آئیں اور پہلی بار چھوٹے ابا نے 1946ء کے ان فسادات کے حوالے سے بہت سے واقعات سنائے۔ اب اُن واقعات کو کیا دہرانا کہ بہار، شمالی ہند، مشرقی پنجاب کے لکھوکھا گھرانوں کے ساتھ وہی کچھ بیتا جو ہمارے گھرانے کے ساتھ بیتا۔ یہ ساری خونچکاں تفصیلات لکھنے والوں نے لکھ ڈالی ہیں۔ سب کچھ کتابوں، افسانوں اور ناولوں میں محفوظ ہوکر ہمارے فسادات کے ادب کا بھی حصہ بن چکا ہے، لیکن ایک واقعہ بتاکر چھوٹے ابا دردمندی کے جذبے سے مغلوب ہوکر پھوٹ پھوٹ کر روپڑے اور میں بے بسی سے انہیں چپ چاپ دیکھتا رہا:
’’بھیا مجھ زخمی کو گود میں اٹھائے لے جارہے تھے۔ میں بھوکا تھا، وہ بھی کئی دن سے بھوکے تھے۔ مجبور و بے قرار ہوکے انہوں نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا تو انہوں نے کہا: بھائی! ہم کئی دن سے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کے لیے ہو تو ہمیں دے دو۔ سننے والے کو رحم آیا، اُس نے ایک روٹی پر سالن رکھ کر دروازے کے پیچھے سے دے دیا۔ بھیا (وہ اپنے بڑے بھائی اور میرے ابی جان کو بھیا کہتے تھے) روٹی اور سالن لے کر کسی کنارے پہ بیٹھ گئے اور نوالہ توڑ توڑ کر مجھے کھلانے لگے۔ حالاں کہ وہ خود بھوکے تھے لیکن انہوں نے سارا کھانا مجھے کھلادیا، خود کچھ نہ کھایا‘‘۔
اتنا کہنا تھا کہ ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ روپڑے۔
کچھ تو مزاج میں اُن کے رقت تھی، کچھ ستم زدہ حالات نے دل میں نرمی اور سوز پیدا کردیا تھا جس کا ایک اور مظاہرہ میں نے اُس وقت دیکھا جس کا تذکرہ میں اپنی بڑی پھوپھی کے خاکے (’’دکھیاری پھوپھی‘‘) میں کرچکا ہوں۔ مختصراً یہ کہ میری پھوپھی اور ان کی بڑی بہن کا بیٹا شاہد جو تقریباً میرا ہم عمر تھا، چیچک کے موذی مرض میں مبتلا ہوا تو چھوٹے ابا غالباً میڈیکل کے آخری سال میں تھے۔ کالج سے واپسی پہ وہ سیدھے اسی کمرے میں چلے جاتے جہاں شاہد لیٹا ہوتا تھا۔ انہوں نے ہمارے خاندانی ڈاکٹر جنھیں اُن کی دراز ریش اور شرعی پہناوے کی وجہ سے ہم لوگ حاجی صاحب کہتے تھے، کے ساتھ مل کر شاہد کو چیچک کی بیماری سے نجات دلانے اور صحت یاب کرنے کی سرتوڑ کوشش کی لیکن قضا و قدر کے فیصلے کے آگے کسی کی کب چلی ہے جو اُن کی چلتی! شاہد کی آنکھیں جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہوئیں تو اس کی موت کی تصدیق کرکے چھوٹے ابا بدنصیب کمرے سے باہر نکلے اور آنگن میں بچھی چوکی کے کنارے پہ بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کے دھاڑیں مار مار کے رونے لگے۔ تب میں سیڑھیوں پہ کھڑا انہیں روتا دیکھتا رہا۔ یہ منظر بھی حافظے میں ایسے روشن ہے جیسے کبھی بجھا ہی نہ ہو۔
چھوٹے ابا نے غالباً اسی سانحے کے اثر سے مغلوب ہوکر ہائوس جاب کے لیے ڈھاکا جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈھاکا میں ملک کے معروف فزیشن ڈاکٹر رب کی زیر نگرانی انہوں نے اپنی عملی تربیت مکمل کی، اور پھر ڈاکٹر رب ہی کے مشورے پر ڈھاکا سے کراچی کا رختِ سفر باندھا۔ ڈاکٹر رب کے سیاسی اور بااثر حلقوں میں بھی مراسم و تعلقات تھے۔ انہوں نے ہی چھوٹے ابا کو سمجھایا کہ حالات دن بدن مخدوش ہوتے جارہے ہیں اور مجھے مشرقی پاکستان کا پاکستان کے ساتھ چلنا مشکل نظر آرہا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم کراچی میں اپنا کیریئر بنائو۔ یہ بات غالباً 1969ء کی ہے۔ چھوٹے ابا کراچی آئے اور یہاں ایئرپورٹ پر آخر آخر کو ہیلتھ آفیسر ہوگئے۔ سعود آباد ملیر میں انہوں نے ایک سو بیس گز پر بنا ہوا دو تین کمروں کا ایک مکان بھی خرید لیا۔ یہی مکان جولائی 1971ء میں ہم لوگوں کی پناہ گاہ بنا۔ چھوٹے ابا کی شادی یہاں آنے کے ایک سال بعد اپنے رشتے دار گھرانے میں طے پائی۔ ابا جان اس شادی میں شرکت کے لیے راج شاہی سے یہاں آئے اور شادی کے کچھ ہی دنوں بعد بیمار ہوکے ہسپتال میں داخل ہوئے۔ چھوٹے ابا نے، جن کی ہر خوشی کسی نہ کسی غم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اپنے بڑے بھائی کی تیمارداری اور خدمت میں کوئی کسر نہ اُٹھا رکھی۔ ابھی نئی نویلی دلہن کے ساتھ انہوں نے پُربہار زندگی کا پوری طرح سے لطف بھی نہ اٹھایا تھا کہ موت نے جھپٹا مارا اور بڑے بھائی کو اٹھا لے گئی۔ ان پہ جو گزری ہوگی اس کا تو کوئی کیا اندازہ کرے، خود راج شاہی میں بہ ذریعہ ٹیلی گرام یہ سنائونی ملی تو سارا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ لیکن ابھی اس گھرانے کو اور بھی کئی روح فرسا قیامتوں سے گزرنا تھا۔ ابا کی موت کے بعد ملک میں عام انتخابات ہوئے اور پھر ملکی قیادت کی عاقبت نااندیشی سے سارا مشرقی پاکستان آگ، خون، موت اور وحشت و درندگی کے الائو میں جل اُٹھا۔ ہمارا گھرانا لٹ پٹ کر سقوطِ ڈھاکا سے چند ماہ قبل آخری بحری جہاز الشمس سے کراچی کی بندرگاہ پر اُترا، تو ساحل پہ چھوٹے ابا کو دیگر رشتے داروں کے ساتھ اپنا منتظر پایا۔ دس پندرہ افراد پر مشتمل یہ کنبہ چھوٹے ابا ہی کے تین کمروں کے مکان میں قیام پذیر ہوا۔ چوں کہ فسادات مکتی باہنی کے درندوں کے ہاتھوں انتخابات کے فوراً بعد ہی شروع ہوچکے تھے، لہٰذا دو ایک رشتے دار گھرانے پہلے بھی کراچی ہجرت کرکے آئے تو چھوٹے ابا کے گھر ہی پہ قیام پذیر ہوئے۔ چھوٹے ابا اور چھوٹی امی نے نہایت دردمندانہ فراخ دلی اور تواضع و مہمان داری کے تمام مشرقی آداب کے ساتھ ان گھرانوں کا خیال رکھا۔ اور ہم لوگ تو چھوٹے ابا ہی کے ساتھ رہے سہے اور پلے بڑھے تھے، لہٰذا ہم لوگوں کے لیے اُن کی کرم نوازی تو ایسی ہی تھی جیسی اپنوں کے ساتھ، سگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے میٹرک کا امتحان سندھ مدرسہ اسکول کے امتحانی مرکز میں دیا۔ راج شاہی بورڈ سے نتیجہ آیا تو چھوٹے ابا نے مجھے اپنے ساتھ لے جاکر جامعہ ملیہ کالج میں داخل کرایا۔ یہ کالج ڈاکٹر محمود حسین وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی کا قائم کردہ تھا اور اس کا شمار کراچی کے بہترین کالجوں میں اُس زمانے میں ہوتا تھا۔ میری لکھنے پڑھنے کی صلاحیتوں کو اس مادر علمی میں بہت جِلا ملی۔ ابتدائی ادبی دوست یہیں بنے جنہوں نے ادبی حلقوں سے مجھے متعارف کرایا۔ پروفیسر عطا اللہ حسینی، پروفیسر وحید اللہ نظمی، پروفیسر حسن علی شطاری اور شاہد اختر جیسے لائق اور مخلص اساتذہ ملے جن کے علم اور تربیت سے استفادہ کیا۔ تو یہ چھوٹے ابا ہی کی شفقت و محبت تھی جس نے علم و ادب کی دنیا میں کچھ کرنے کا حوصلہ دیا۔
سقوطِ ڈھاکا کے بعد ایک اور سانحہ گزرا کہ ابی جان یرقان کے مرض میں مبتلا ہوئے اور دس پندرہ دن کے اندر ہی چٹ پٹ ہوگئے۔ تب چھوٹے ابا کی سعودی عرب کے شہر نجران کے ایک ہسپتال میں ملازمت ہوگئی تھی، ابی جان کی رحلت کے بعد چھوٹے ابا ہی نے ہمارے گھرانے کی کفالت کی، اور جب تک اپنے پائوں پہ ہم سب بھائی کھڑے نہیں ہوگئے، ان ہی کے مکان میں رہتے رہے۔ چھوٹے ابا سعودی عرب سے قسمت آزمانے امریکہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے نہایت محنت اور جدوجہد سے سائیکاٹری کی تعلیم مکمل کی۔ 1990ء کی دہائی میں اِس خاکسار پہ ڈپریشن کا دورہ پڑا اور طبیعت ایسی بگڑی کہ زندگی ہی سے مایوس ہوگیا، اس موقع پر بھی چھوٹے ابا ہی کام آئے۔ انہوں نے بہ ذریعہ ٹیلی فون نہ صرف مجھ سے رابطہ قائم رکھا، دوائیں تجویز کیں، قیمتی مشورے دیے، حوصلہ بڑھایا بلکہ گاہے بہ گاہے قیمتی دوائیں بھی وہاں سے آنے والوں کے ہاتھوں بھجواتے رہے۔ خداوند تعالیٰ اس کا انہیں اجرِ عظیم عطا فرمائے (آمین)
سائیکاٹرسٹ کی حیثیت میں امریکہ میں انہوں نے ایک ہسپتال میں ملازمت بھی کی اور اپنا مطب بھی قائم کیا۔ امریکہ میں جو ذہنی اور نفسیاتی عوارض عام ہیں اس کی بابت اُن کا تجربہ اور مشاہدہ بہت وسیع ہے۔ چوں کہ بہ حیثیت ڈاکٹر مرض کی تشخیص میں انہیں ہمیشہ سے بہت مہارت حاصل رہی ہے، اور مریضوں کا علاج بھی ہمدردی اور محبت و تواضع کے ساتھ کرتے رہے ہیں تو آج بھی امریکی مریض ان سے علاج معالجے کے لیے رابطہ کرتے رہتے ہیں۔ حالاں کہ انہیں ریٹائرمنٹ لیے بھی کئی برس گزر چکے ہیں۔ پچھلے سے پچھلے برس وہ اعتکاف کرنے بیت المقدس گئے اور وہیں مقدس مسجد اقصیٰ میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزارا۔ اپنے دین کی محبت ان کے خمیر میں شامل ہے۔ وطنِ عزیز سے دور ہوکر بھی اس وطن کی فکر انہیں فکرمند رکھتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس کی بنیادوں میں لاکھوں مسلمانوں کے ساتھ اُن کا لہو بھی تو شامل ہے۔