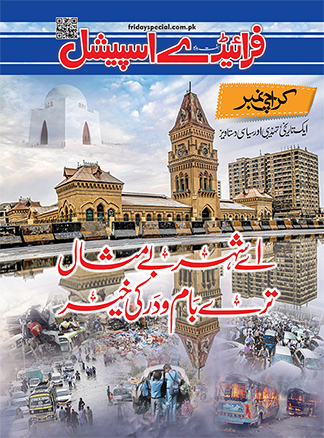آج بھی کیمپس کی اس چھوٹی سی مسجد کے صحن کی منڈیر پر نمازِ مغرب سے ذرا پہلے جاکر بیٹھتا ہوں تو ایسا شبہ ہوتا ہے کہ دُور سڑک پہ ڈاکٹر ریاض الاسلام صاحب خراماں خراماں چلے آرہے ہیں۔ آکر وہ میرے سلام کا جواب سر کے اشارے سے دیں گے، مصافحہ فرمائیں گے اور پھر منڈیر پر ساتھ ہی بیٹھ جائیں گے۔ حال احوال پوچھنے کے بعد یہ پوچھنا نہ بھولیں گے ’’اور علمی مصروفیت کیا ہے؟‘‘
ایک عالم، ایک اسکالر کی اور کیا دل چسپی ہوسکتی ہے! جیسے کاروباری آدمی کاروبار، اور سیاسی آدمی سیاست کی بابت جاننے کے لیے مشتاق رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑے اسکالر تھے، بلکہ یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ اسکالروں کے اسکالر اور عالموں کے عالم تھے۔ زندگی ساری حصولِ علم اور فروغِ علم میں فنا کردی تھی۔ اہلِ علم اور اساتذہ ایک پی ایچ ڈی مر کھپ کے کرتے ہیں، اور بعض تو اسی کو تحقیق کی آخری سیڑھی سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر ریاض الاسلام صاحب نے دو پی ایچ ڈی کررکھی تھی، ایک علی گڑھ مسلم یونی ورسٹی سے، دوسری کیمبرج یونی ورسٹی سے۔ رہنے والے ریاست رام پور کے تھے (تاریخ پیدائش 30 دسمبر 1919ء)۔ گھرانا مذہبی تھا۔ خود تو گہرے مذہبی آدمی نہ تھے لیکن شام کو سیر کرکے واپس لوٹتے ہوئے اسی مسجد میں نماز ادا کرنے کی عادت سی تھی۔ پستہ قامت، آنکھوں پہ عینک، چہرے پہ سنجیدگی مگر بشاشت کے ساتھ، سر پہ بال جتنے بھی رہ گئے تھے انھیں سلیقے سے کاڑھے رہتے تھے۔ آنکھیں کسی قدر روشن اور ہونٹ مسکرانے کے لیے تیار۔ آواز دھیمی مگر صاف۔ نماز پڑھتے ہوئے ٹوپی کا اہتمام کرتے کبھی نہ دیکھا۔ پہلی صف کے بالکل آخری کونے میں جاکر کھڑے ہوجاتے۔ صف کبھی بھر جاتی تھی، کبھی نہیں بھرتی تھی، وہ فقہ کے مسئلے مسائل سے بے نیاز امام کے ساتھ سلام پھیر کر عموماً رخصت ہوجاتے تھے۔
ڈاکٹر صاحب سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، پہلی ملاقات میرے زمانۂ طالب علمی میں ہوئی تھی۔ وہ تاریخِ عمومی کے شعبے میں پروفیسر اور ڈین فیکلٹی آف آرٹس تھے۔
یونین کے میگزین ’’الجامعہ‘‘ کے لیے میں نے اُن کا انٹرویو کیا تھا۔ اس انٹرویو اور دورانِ انٹرویو ہونے والی گفتگو کا کوئی تاثر اب ذہن میں محفوظ نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ ڈاکٹرصاحب تب بھی پرانی وضع کے بزرگ، مشفق و مہربان، وضع دار اور رکھ رکھائو والے لگے تھے۔ یہ تاثر اتنا گہرا تھا کہ اُن سے جب بھی ملا، نہایت تہذیب، تمیز سے ادب آداب کے ساتھ ملنے پر خود کو مجبور پایا۔ ممکن ہے اس تعظیم میں اُن کے تبحر علمی کا رعب بھی رلا ملا ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اُن کے علمی مقام و مرتبے کا بہت دنوں بلکہ برسوں تک اندازہ ہی نہ ہوسکا۔ انھیں دانش وری اور دانش ورانہ گفتگو کا ہرگز شوق نہ تھا۔ اپنے علم کی نمائش کرتے ہوئے تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ بعد میں جب اُن سے مسجد کے تعلق سے اک ذرا قربت نصیب ہوئی تو علمی استفسارات کا جواب بھی نہایت سادگی سے دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کیمپس ہی میں قیام پذیر تھے۔ ملازم نے گھنٹی پر گیٹ کھولا۔ نام پوچھ کر اندر گیا اور پھر واپس آ کے اس نے مجھے اوپر کی منزل پہ پہنچا دیا جہاں ان کی لائبریری تھی۔ مجھے دیکھ کر شفقت بھری مسرت کا اظہار کیا۔ میری نظریں شیلف پر سجی کتابوں کا طواف کرنے لگیں۔ انگریزی، فارسی اور اردو کی موٹی موٹی کتابیں، تاریخ، تصوف وغیرہ کے موضوع پر نہایت سلیقے سے رکھی تھیں۔ پھر باتیں شروع ہوگئیں۔ اب وہ باتیں تو ذہن سے محو ہوگئی ہیں ہاں مگر یہ ضرور یاد ہے کہ تاریخ ہی کے شعبے کے ایک نوجوان استاد ہاتھوں میں کیٹلاگ اٹھائے کمرے میں داخل ہوئے، ڈاکٹر صاحب نے ان کا تعارف کرانا چاہا تو میں نے عرض کیا کہ ان سے اچھی طرح واقف ہوں۔ پھر انھوں نے بتایا کہ یہ میری نگرانی میں (غالباً) اورنگ زیب کے عہد پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں لیکن میں نے ان سے کہہ رکھا ہے کہ بھئی مغل عہد پر تحقیق فارسی سیکھے بغیر کیسے ممکن ہے! تو یہ آج کل فارسی سیکھ رہے ہیں۔ پھر انھوں نے ان نوجوان محقق کی ذہانت اور ذوقِ علمی کی تعریف کی جس سے شاید ان کی حوصلہ افزائی مقصود تھی۔ وہ جس مشقت اور علمی انہماک اور معیارِ تحقیق کی توقع اُن سے وابستہ کررہے تھے، وہ نوجوان محقق اس پر پورے نہ اتر سکے اور جلد ہی میدان چھوڑ گئے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ نگران مقالہ ایسی کوئی شرط اپنی زیر نگرانی تحقیق کرنے والوں پر عاید ہی نہیں کرتے۔ عربوں کی تاریخ، عربی تمدن پر تحقیقی کام عربی سیکھے اور جانے بغیر محققین کرتے ہیں، سارا کام اردو ترجموں کی مدد سے کرلیا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ترجمہ تو پھر ترجمہ ہوتا ہے، اصل کا بدل نہیں ہوتا، اور بعض ترجمے تو حد درجہ ناقص ہوتے ہیں۔
ڈاکٹر ریاض الاسلام اُس تہذیب کے پروردہ تھے جب استاد فی الواقع استاد ہوتا تھا۔ انھیں اپنے زمانۂ طالب علمی میں نہایت عمدہ، نہایت اچھے اساتذہ ملے۔ ذہین اور محنتی تو شروع سے تھے، ابتدائی ثانوی تعلیم اعلیٰ امتیاز کے ساتھ مکمل کی اور سر رضا خان طلائی تمغا حاصل کیا۔ تاریخ کے مضمون میں ایم اے کرنے کے چار سال کے اندر 1946ء میں علی گڑھ مسلم یونی ورسٹی سے پی ایچ ڈی کرلی۔ مقالہ اُن کا فیروز شاہ تغلق کی زندگی اور ان کے عہد کی تہذیب و ثقافت کی بابت تھا۔ علی گڑھ میں بھی انھیں علمی فضا میسر آئی۔ محمد حبیب، اے بی اے حلیم (جو بعد میں کراچی یونی ورسٹی کے وائس چانسلر ہوئے)، شیخ عبدالرشید اور معین الحق جیسے اساتذہ سے انھوں نے بہت کسبِ فیض کیا۔ پھر خود بھی درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہوگئے۔ دو سال تک سینٹ اسٹیفن کالج دہلی میں پڑھایا۔ پاکستان بنا تو ہجرت کرکے یہاں آگئے۔ تین برس پنجاب یونیورسٹی میں تدریس میں گزارے۔ دو ایک برس شعبۂ آرکائیوز میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر کام کیا، پھر 1953ء میں کراچی یونی ورسٹی کے شعبۂ تاریخ میں ایسوسی ایٹ پروفیسر مقرر ہوئے۔ پھر اِدھر دیکھا نہ اُدھر… زندگی ساری اسی مادرِ علمی کی نذر کردی۔ البتہ درمیان میں غالباً تقرر کے چار سال بعد کیمبرج یونی ورسٹی لندن چلے گئے اور وہاں ہند ایران تعلقات پر مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ایک اور ڈگری سے خود کو متصف کیا۔ جہاں تک مجھے علم ہے اُنھیں وائس چانسلرشپ کی بھی آفر تھی، لیکن انھوں نے انتظامی جھمیلوںمیں پڑنا پسند نہ کیا۔ ان سے پہلے ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی نے بھی جو ڈاکٹر محمود حسین وائس چانسلر کی ناگہانی وفات کے بعد قائم مقام وائس چانسلر بنے، مستقل تعینات ہونے سے معذرت کرلی۔ حالاں کہ تاریخ کے مضمون کے دو پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اور ڈاکٹر محمود حسین وائس چانسلر بھی رہے اور علمی و تحقیقی کام بھی کیا۔ ہمارے ڈاکٹر ریاض الاسلام صاحب شاید اس حقیقت سے واقف تھے کہ وائس چانسلری قبول کرنا بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے سے کم نہیں، چناں چہ یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ بھئی لکھنے پڑھنے میں میری دل چسپی ہے، انتظامی کاموں میں پڑنا نہیں چاہتا۔ اور بات ٹھیک بھی تھی۔ ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کی معذرت کے بعد شعبۂ معاشیات کے ڈاکٹر احسان رشید پسر پروفیسر رشید احمد صدیقی نے یہ منصب قبول کیا تو انجامِ کار قبل از میعاد مستعفی ہوئے کہ کرسی اُن کی ایک طلبہ تنظیم کے جیالوں نے یونیورسٹی گرائونڈ میں اپنی طاقت کے مظاہرے کے طور پر نذرِ آتش کردی۔ وہ زمانہ اور تھا، وہ شخصیتیں بھی ایسی تھیں کہ عزتِ سادات کو منصب اور عہدے سے زیادہ عزیز جانتی تھیں۔ حکومت کو غیرت آئی تو انھیں اردن میں سفیر بناکر رخصت کردیا۔ تو اگر ڈاکٹر ریاض الاسلام صاحب نے اس عہدۂ جلیلہ جو امتدادِ زمانہ اور پستیٔ احوال و کردار سے عہدۂ رذیلہ بنتا جاتا ہے کہ یونی ورسٹی کے ہر کس و ناکس کو یہ حق حاصل ہوجاتا ہے کہ جب چاہے کسی معمولی سی شکایت پر بھی وائس چانسلر کی دستارِ فضیلت سے کھیلنے لگے، خواہ وہ ’’باشعور طلبہ‘‘ کے نمائندے ہوں یا ’’معزز اساتذہ‘‘ یا ’’مظلوم ملازمین‘‘ کے لیڈرانِ کرام۔ ڈاکٹر ریاض الاسلام نے ڈین بننے ہی کو کافی جانا۔ مزید ترقی کی آرزو سے کنارہ کشی اختیار کی تاکہ حقیقی لذت و مسرت جو علمی کاموں سے ملتی ہے اُس پر ایسے ایک نہیں سینکڑوں مناصب اور عہدے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ 1979ء میں ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہوگئے لیکن یونی ورسٹی نے ان کی علمی خدمات سے طلبہ اور اساتذہ کے استفادے کے لیے انھیں پروفیسر ایمریطس بنا دیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے انسٹی ٹیوٹ آف دی سینٹرل اینڈ ویسٹ ایشین اسٹڈیز جیسے تحقیقی و تصنیفی ادارے کا بہ طور سیکرٹری انتظام بھی سنبھال لیا، ہرچند کہ ادارے کو یونی ورسٹی کی جانب سے صرف پانچ ہزار روپے سالانہ کی گرانٹ ملتی تھی۔ بعد میں ہمدرد فائونڈیشن نے ایک لاکھ کا عطیہ دینا شروع کیا۔ تین برس بعد وہ بھی بند ہوگیا۔ ان مالی مشکلات کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے اس ادارے سے 20 کتابیں شائع کیں جو علمی اور تحقیقی اعتبار سے بلند معیار کی حامل تھیں۔ خود ڈاکٹر صاحب کی اپنی اعلیٰ تحقیقی کتابوں کی تعداد عارف نوشاہی کے مطابق چھے سے زیادہ نہ تھی۔ بڑے اسکالر، بڑے محقق پتا مارکر جس دیدہ ریزی سے علمی کام کرتے ہیں کہ توجہ معیار پر ہی مرکوز رہتی ہے، برسہا برس ایک ہی کتاب کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں۔ سو ایسے کام پر ’’سو سنار کی، ایک لوہار کی‘‘ والا محاورہ صادق آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی دو کتابیں تاحال غیر مطبوعہ ہیں۔ ان کی آخری کتاب جو اُن کی زندگی میں آکسفورڈ پریس سے شائع ہوئی، انگریزی میں تھی جس کا عنوان تھا: “Sufism in south Asia: Impact of Fourteenth Century Muslim Society” (جنوبی ایشیا میں تصوف: چودھویں صدی کے مسلمان معاشرے پر اثرات)
ڈاکٹر صاحب کی کسرِنفسی کے دو واقعات محض یہ بتانے کے لیے کہ جو متبحر عالم ہوتا ہے اُس میں کتنی عاجزی اور فروتنی ہوتی ہے۔
ان کی مذکورہ آخری کتاب آکسفورڈ سے خرید کر میں ان کی خدمت میں دستخط کرانے گیا تو انھوں نے اظہارِ مسرت کیا، نہایت شفقت سے کتاب لی اور لکھا:
“Presented to my dear friend with kind regards”
ذرا تصور کیجیے۔ علم و فضل کے مقام کے فرق کا تو خیر ذکر ہی کیا، انھوں نے عمر کے تفاوت کا بھی خیال نہ کیا۔ ہاں شاخِ ثمردار جھک جاتی ہے اور برگ و بار سے خالی ٹہنی جو ہوتی ہے وہ اکڑی رہتی ہے۔
اگلا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ڈاکٹر صاحب نے فرمایا: ’’بھئی کسی دن اپنی لائبریری تو دکھائیے۔‘‘
عرض کیا: ’’جناب میری خوش نصیبی۔ جب چاہیں، جب حکم دیں۔‘‘
کہنے کو تو کہہ دیا مگر کچھ محجوب بھی ہوا کہ میری لائبریری میں ایسا کیا ہے! ساری کتابیں ڈاکٹر صاحب نے دیکھ رکھی ہوں گی، یا بہت سی تو ان کے دیکھنے کے قابل بھی نہ ہوں گی۔ چناں چہ ایک شام غریب خانے پر تشریف لائے۔ کتابیں ملاحظہ فرماتے ہوئے کچھ کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا بھی۔ البتہ مکتبہ جامعہ ملیہ دہلی سے عماد الحق فاروقی کی چھپی ہوئی کتاب ’’دنیا کے بڑے مذہب‘‘ (جو تب تک یہاں نہیں چھپی تھی) کے چند صفحات پڑھ کر اسے لے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ خاکسار پہلے بھی کہیں لکھ چکا ہے کہ کتاب عاریتاً دینے میں کچھ ایسا فراخ دل نہیں، سابقہ تلخ تجربات کی وجہ سے کہ لوگ پڑھیں یا نہ پڑھیں، کتاب لے کر واپس نہیں کرتے، اس لیے کوئی کتاب عاریتاً بھی مانگتا ہے تو کلیجہ منہ کو آجاتا ہے۔ خدا گواہ ہے یہ پہلا موقع تھا کہ کتاب مانگے جانے پر فخر محسوس ہوا۔ یعنی یہ نالائق اور اس کی چھوٹی سی لائبریری میں ایک کتاب ایسی بھی تھی جسے ڈاکٹر ریاض الاسلام جیسی علمی ہستی پڑھنے کے لیے ساتھ لے جانے کی خواہش مند ہوئی۔ میں نے جھٹ سے کہا:’’ڈاکٹر صاحب ضرور۔ جو کتاب بھی لے جانا چاہیں، حاضر ہے۔‘‘
اب آگے کی سنیے۔ کچھ ہی عرصے بعد ایک روز گھر آیا تو ایک خاکی لفافہ رکھا تھا۔ لفافے پر اپنا نام لکھا دیکھ کر پہچان گیا کہ ڈاکٹر صاحب کی ہینڈ رائٹنگ ہے۔ وہ اس سے پہلے کسی نہ کسی سلسلے میں دو ایک دفعہ مجھے رقعات لکھ چکے تھے، اس لیے اُن کی تحریر سے آشنا تھا۔ لفافہ کھولا تو وہی کتاب تھی اور ساتھ شکریے کا خط۔ احساسِ ذمے داری اور ایمان داری کا ایسا متاثر کن مظاہرہ کاش سارے اہلِ علم کا شعار بنے۔ جب یہ رشتہ استوار ہوا تو ایک دن خاکسار نے بھی اُن کی لائبریری سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ؒ کے ملفوظات کا مجموعہ ’’ فوائد الفواد‘‘ از حسن سجزی؟؟؟؟، ہمت کرکے بہ غرضِ مطالعہ طلب کیا، بہ خوشی اجات مرحمت فرما دی۔ میرے پاس اس کتاب کا پاکستانی ایڈیشن تھا جو ایڈیٹنگ کے عمل سے گزرکر خاصا مختصر ہوگیا تھا۔ ہندوستانی ایڈیشن ترجمے اور طباعت دونوں اعتبار سے خاصا بہتر اور ضخیم تھا۔ افسوس کہ کتاب کا مطالعہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے بعد بیماری داعیٔ اجل کو لبیک کہا۔ ان کی وفات کے بعد ان سے عاریتاً لی ہوئی کتاب ضمیر پر بوجھ بن گئی۔ ایک دن ڈاکٹر سید جعفر احمد تشریف لائے تو اس خیال سے کہ ڈاکٹر صاحب کے انسٹی ٹیوٹ کی ذمے داری انھوں نے ہی سنبھال رکھی تھی، کتب خانہ بھی ان ہی کے زیر انتظام تھا، یہ کتاب ان کے حوالے کردی۔
ڈاکٹر صاحب کو ہرچند کہ حکومت نے ان کی علمی و تحقیقی خدمات کے اعتراف میں ’’ستارۂ امتیاز‘‘ سے نوازا، لیکن حقیقتاً وہ اس سے بڑے اعزاز کے مستحق تھے۔ عام تعلیم یافتہ لوگ بے شک ان کے نام اور مقام سے لاعلم تھے، لیکن علمی حلقوں میں انھیں جو احترام حاصل تھا، اس کی وجہ ان کا باوقار عالمانہ رویہ تھا۔ یہ الگ بات کہ… اور یہ واقعہ بلکہ سانحہ… خاصے ردو کد کے بعد کہ لکھوں یا نہ لکھوں… لکھتا ہوں کہ ایک وائس چانسلر جو ادبی حلقوں میں بھی معروف ہیں، ان سے بہ حیثیت چیئرمین شعبہ دفتری کام سے ملنے گیا تو انتظار گاہ میں ڈاکٹر صاحب کو بھی وائس چانسلر صاحب سے ملنے کے لیے اپنی باری کا منتظر پایا۔ ان کے ہاتھ میں آکسفورڈ والی ان کی کتاب تھی جو وہ سربراہِ ادارہ کو پیش کرنے کے لیے لائے تھے۔ کسی صوفی کی سی کسر نفسی اور انکسار کا پیکر بنے بیٹھے تھے۔ میں جانتا تھا کہ سنڈیکیٹ یا کسی انجمنِ اساتذہ کے عہدے دار کو وائس چانسلر سے ملنے کے لیے انتظار گاہ میں بیٹھنے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی۔ وہ بلا جھجک دروازہ کھول کر اندر چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنے نام کی پرچی اندر بھجوا چکے تھے، وائس چانسلر صاحب کو یہ بھی توفیق نہ ہوئی کہ باہر آکر مل لیتے یا اندر ہی بلاکر بٹھا دیتے اگر میٹنگ کی ایسی ہی مصروفیت تھی تو۔ آدھے گھنٹے کا انتظار کھینچنے کے بعد مجھ سے ایک عالم کی یہ ناقدری بلکہ ہتک برداشت نہ ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کو کسی کام کا کہہ کر اجازت لی۔ دفتر واپس آکر اپنی وہ کتاب جو وائس چانسلر صاحب کو پیش کرنے کے لیے اُن کا نام بھی لکھ کر دستخط کرچکا تھا، اسے قلم زد کردیا اور کتاب سیمینار لائبریری کو بہ طور عطیہ بھجوا دی۔
عالم کا احترام علم کا احترام ہے۔ مادرِ علمی کا زوال اگر ہے تو اس کے سوا کوئی اور سبب نہیں اس کا کہ سیاست علم اور عالم پر غالب کردی گئی ہے!