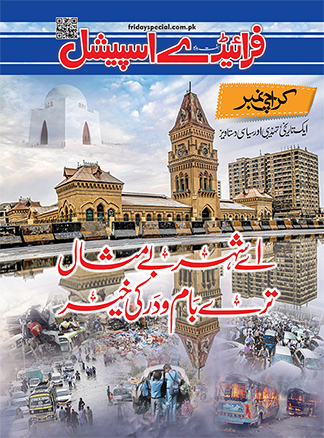یہ اُن دنوں کی بات ہے جب کراچی امن و شانتی کا شہر ہوتا تھا۔ راتیں جاگتی تھیں، شام کو سمندر سے بہہ کر آنے والی ہوائیں دل کو اداسی اور احساسِ تنہائی سے بھر دیتی تھیں۔ میں ملیر سعود آباد میں رہتا تھا، کالج کا طالب علم تھا۔ اکثر میں بھوری آنکھوں اور دہکتے ہوئے سرخ و سپید چہرے والے پستہ قامت شخص کو سامنے سڑک سے گزرتے دیکھتا تھا۔ کچھ کھویا کھویا سا، اپنے اندر ڈوبا ہوا یہ آدمی راہ چلتے ہوئے بھی اِدھر اُدھر متلاشی نظروں سے دیکھتا، دوسروں سے الگ تھلگ بڑا اکیلا اکیلا سا لگتا تھا۔ میں نے اسے جب بھی دیکھا، اسی حال میں پایا۔ جی بہت چاہتا تھا اسے روکوں اور پوچھوں آپ ہیں کون؟ کس کی تلاش میں ہیں؟ لیکن سوچتا ہی رہ گیا۔ پوچھ نہ سکا، شاید اس خیال سے کہ اس کی تنہائی اور خاموشی کو ٹھیس پہنچانا اچھا نہیں۔ میں اس شہر میں نووارد تھا اور ابھی پورے طور پر شہر کو سمجھ سکا تھا اور نہ یہاں کے لوگوں کو۔ پھر یوں ہوا کہ ان ہی دنوں کالج میں ناصر کاظمی کی یاد میں ایک ادبی تقریب ہوئی۔ صدارت استاد اور معروف دانش ور پروفیسر کرّار حسین کی تھی۔ اس محفل میں شرکت کے لیے نثری نظم کو تحریک کی شکل دینے والے نقاد اور شاعر قمر جمیل آئے تھے۔ ان ہی کے ساتھ، ہاں میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، ان کے ہمراہ وہی بھوری آنکھوں اور دہکتے ہوئے چہرے والا کھویا کھویا، اپنے آپ میں ڈوبا ہوا وہ آدمی بھی تھا جس نے کھدر کی شلوار قمیص پہن رکھی تھی اور جسے میں کئی بار سعود آباد سے گزرنے والی سڑک پہ آتے جاتے دیکھ چکا تھا۔ اس کی اجنبیت بھی میرے لیے اتنی مانوس ہوچکی تھی کہ کالج میں اسے دیکھ کر حیران تو ہوا، ساتھ ہی اطمینان بھی ہوا کہ آج جان سکوں گا کہ یہ اجنبی ہے کون؟تقریب کے بعد میرے دوست اور شاعر شوکت عابد نے مجھے ان سے یہ کہہ کر ملوایا کہ یہ احمد ہمیش ہیں، کہانی کار اور شاعر۔ میں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہمیش جی نے اپنا نرم گدیلا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک گرمی اور نرمی میری ہتھیلی میں منتقل ہوگئی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ دُور اور کہیں دیکھ رہے تھے۔ یعنی انھوں نے مجھے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ ماحول میں لڑکے لڑکیوں کی بھیڑ میں تھے اور نہیں بھی۔ اس مشاہدے نے ان کی ذات میں میرے استعجاب کو اور بڑھا دیا۔ نہیں یاد مجھے کہ اس پہلی باضابطہ ملاقات میں ان سے کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہو کہ جو یاد رہ سکے۔ ملنے ملانے کا کوئی ایسا موقع تھا بھی نہیں کہ طلبہ اور اساتذہ سبھی کرّار صاحب کی مسحور کن گفتگو اور اُم حبیبہ کی ناصر کاظمی کی گائی ہوئی غزل ’’گئے دنوں کا سراغ لے کے کدھر سے آیا کدھر گیا وہ‘‘کے ایسے اثر میں تھے کہ فضا اداسی سے بھرگئی تھی، لگتا تھا ناصر کاظمی کی غمگین روح بھی آس پاس کہیں موجود رہی ہوگی۔ ایک دن کسی ادبی رسالے کی ورق گردانی کرتے ہوئے ایک نظم پر ٹھیر گیا۔ نظم کے خالق کا نام تھا : احمد ہمیش۔ اور نظم تھی: گیانی جی یہ تو بتلائوتم ان جادو کی زنجیروں والے شہر میں رہ کےسنگینوں والے شہر میں رہ کے کون سی شبھ گھڑیوں کے سپنے دیکھ رہے ہو
……..***…….
دیکھو اس دیوار کے پیچھےپانی کی چاہت کے کارن بے بس اور ناکام امیدیں ننگے پائوں چلتے چلتے ہار گئی ہیںایسے میں اب زیادہ رکنا ٹھیک نہیں ہے گیانی جی اب زیادہ رکنا ٹھیک نہیں ہے آئو چلیں اس شام کے پردے میں چھپ جائیں شام جو ہم دکھیوں کی ماں ہے یہ نظم… ہاں اس نظم نے مجھ پر جادو سا کردیا۔ میں اسے بار بار پڑھتا تھا۔ یہاں تک کہ یہ مجھے زبانی یاد ہوگئی۔ آج تک یاد ہے۔ اب ہمیش جی کی ذات میں میری دل چسپی بڑھ گئی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ پراسرار سا آدمی جو شاعر بھی ہے، کہانی کار بھی، اسی کرّے کا باشندہ ہے۔ وہ مجھے کہیں اور، کسی اور سیارے سے آیا ہوا لگتا ہے۔ تو دلچسی اور استعجاب تو یقینا اس کی ذات میں پیدا ہوگئے، لیکن ملاقات کی خواہش اندر جنم نہ لے سکی۔ مجھے ویسے ہی اچھا لگا کہ اسے سڑک پر آتے جاتے، کھوئے اور ڈوبے ہوئے دُور سے دیکھوں۔ اور کسی دن کسی ادبی پرچے کی لاپروائی سے ورق گردانی کرتے ہوئے اس کی کسی نظم پر ٹھیر جائوں اور اسے بار بار پڑھوں، یہاں تک کہ وہ نظم میرے حافظے میں کبھی نہ مٹنے کے لیے اپنی جگہ بنالے۔ کالج کے دن پورے کرکے یونی ورسٹی پہنچا تو وہاں ایک اور حیرت انگیز منفرد شاعر سے دوستی مقدر بنی۔ محمود کنور، یہ راجپوت شاعر جو شاعروں اور ادیبوں سے بھرے پرے شہر میں بالکل اکیلا تھا۔ بعد میں کھلا کہ ان کا واحد غم گسار اگر کوئی ہے تو اس کا نام ہے احمد ہمیش۔ اُس وقت تک ہمیش جی سعود آباد سے عزیز آباد کا سفر طے کرچکے تھے۔ وہ محمود کنور اور قمر جمیل کے گھروں سے قریب ہی رہائش پذیر تھے اور نثری نظم کو ایک مستقل شعری صنف کے طور پر اردو ادب میں رواج دینے کے قضیے میں الجھے ہوئے تھے۔ احمد ہمیش کو ہندوستان سے آئے بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ وہ ریڈیو پاکستان کی ہندی سروس سے منسلک تھے۔ ہندی زبان پہ عبور تھا۔ ہندوستان کے شہر بلیا میں رہتے ہوئے انھوں نے جو کہانیاں لکھی تھیں، ان میں ایک کہانی ’’مکّھی‘‘ تھی جو ادبی دنیا میں مرکزِ توجہ بن گئی تھی۔ جب وہ یہاں آئے تو ’’مکّھی‘‘ کی شہرت کو ساتھ لائے تھے، اور ان کا یہ اعزاز بھی قمر جمیل کے حلقے میں مستند سمجھا جاتا تھا کہ اولین نثری نظمیں اردو میں انھوں نے ہی لکھی تھیں۔ یہ جھگڑا بعد میں اٹھا کہ اگر نثری نظم واقعی شاعری ہے تو یہ تجربہ بہت پہلے اردو میں سجاد ظہیر کرچکے ہیں جن کی طویل نثری نظم ’’پگھلا نیلم‘‘ کی صورت میں چھپ چکی تھی۔ یہ الگ بات کہ سجاد ظہیر نے اسے شعری صنف کے طور پر پیش نہیں کیا تھا۔ ہمیش جی نے اپنے آپ کو ہمیشہ پہلے نثری نظم نگار کی حیثیت میں پیش کیا۔ قمر جمیل صاحب اور محمود کنور وغیرہ نے اُن کے اس دعوے کی تصدیق کی۔ احمد ہمیش بھی محمود کنور کی طرح اپنی ذات اور اپنی شاعری کی بابت بہت حساس تھے۔ دونوں کا اندازِ زیست بھی دنیا داری سے دُور اور شاعرانہ تھا۔ ادب و شاعری ان کی پہلی ترجیح ہی نہیں کُل وقتی سرگرمی تھی۔ کوئی ملاقات، کوئی محفل ایسی نہیں یاد جب ادب کے سوا کوئی اور موضوع زیر بحث آیا ہو۔ اب ادبی دنیا میں مقام و مرتبہ بنانے کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ یہ بھی منصوبہ بندی کا تقاضا کرتا ہے۔ حلقہ بندی، گروہ بندی، تعلقات و مراسم کا اہتمام، بلکہ آج کی زبان میں تعلقات سازی، من تورا حاجی بگویم… پر عمل وغیرہ کے بغیر ادبی سند اور شہرت بھی محض تخلیقات کے بل بوتے پر کہاں ملتی ہے؟ احمد ہمیش اس معاملے میں ہیٹیےتھے۔ اپنے آگے کسی کو کہاں گردانتے تھے! کمزور معاشی بنیاد پر کھڑے ہوکے کوئی کتنا اور کیسا ہی بڑا تخلیق کار ہو، اپنا ہی گن گائے تو تحقیر و استہزاء کے ذریعے اس کے قد کو بڑھنے کب دیا جاتا ہے۔ کیا شبہ تھا کہ ہمیش جی میں ایک سچا اور بڑا فنکار چھپا تھا۔ شاعری اور کہانی دونوں اصناف میں ان کا اپنا اسلوب، اپنے موضوعات، دوسروں سے مختلف ان کی اپنی آواز تھی۔ لیکن قمر جمیل کے چھوٹے سے حلقے کو چھوڑ کر ان کے تخلیقی امکانات اور جو کچھ اب تک انھوں نے اپنی نگارشات پیش کی تھیں، اس کی گواہی کہیں سے نہ آتی تھی۔ جہاں کہیں بھی احمد ہمیش کا نام آتا، ایک استہزائی مسکراہٹ ان ہونٹوں پر دوڑ جاتی، ادب جن کا سنجیدہ مسئلہ کبھی رہا ہی نہ تھا۔ حلقۂ اربابِ ذوق کے ایک اجلاس کا تو میں عینی شاہد ہوں جب احمد ہمیش نے تبصرے و تجزیے کے لیے اپنی نظم پیش کی۔ نظم کی نقول تقسیم کرنے کے خیال سے جب انھوں نے کاغذ شاعر و افسر ضیاء جالندھری کی جانب بڑھایا تو غصے سے ان کا چہرہ تمتما اٹھا اور انھوں نے حالتِ جلال میں کاغذ جس پر ہمیش جی کی نظم درج تھی، لے کر اسے ہوا میں اڑا دیا۔ کاغذ ہوا میں ڈولتا، ڈگمگاتا، خود ان ہی کے قدموں میں آگرا جسے اٹھانے کی انھوں نے زحمت نہ کی۔ اگر وہ اسے اٹھا کر پڑھ لیتے تو اس کی ابتدائی دو لائنیں کچھ ایسی تھیں: یہ کاغذ جو تمہارے ہاتھ میں ہے اسے تمہاری حماقت ہوا میں اڑا سکتی ہے اور نہ اسے آگ جلا ہی سکتی ہے موصوف کو پڑھنے کی ضرورت یوں نہ تھی کہ ہمیش جی نے یہ لائنیں پڑھ کر ہی کاغذ پہلے ان ہی کی طرف بڑھایا۔ چناں چہ غصہ ان کا بے جا یوں نہ تھا کہ اپنے آپ کو انھوں نے نظم کا مخاطب سمجھ لیا۔ معنی فی بطن شاعر کے مصداق یہ تو ہمیشن جی ہی کو معلوم تھا کہ نظم کا مخاطب تھا کون؟ لیکن یہ بھی ہے کہ نظم کی اوپری دو لائنوں کو پڑھ کر ضیاء صاحب کی طرف نظم کی نقل بڑھانے میں کوئی نہ کوئی اشارہ پوشیدہ تو تھا جسے سمجھنے اور محسوس کرنے میں انھوں نے ذرا بھی دیر نہ کی۔ ہمیش جی ریڈیو سے وابستہ تو تھے لیکن تھے ڈرامہ کے آدمی۔ اداکاری کی طرف رخ کرتے تو بہت سوں کے چراغ گل کردیتے۔ اس کا اندازہ یوں ہوا کہ کسی ادیب کی وفات پر تعزیتی جلسے سے خطاب کرنے والوں میں ان کا نام بھی شامل تھا۔ باری آنے پہ نام پکارا گیا تو آہستہ آہستہ قدموں چلتے ہوئے اسٹیج پر دھرے روسٹرم پر پہنچے۔ خاموش کھڑے خلاء کو اپنی مغموم نگاہوں سے گھورتے رہے۔ حاضرین منتظر کہ اب کچھ کہیں گے، لیکن ان کا غمگین چہرہ روسٹرم پر کچھ دیر کے لیے طلوع رہا اور پھر غروب ہوگیا۔ کچھ بھی بولے بغیر وہ اسٹیج سے اتر آئے۔ بعد میں کسی نے پوچھا اس حرکت کا مطلب؟ کسی گیانی کی طرح اس راز پر سے یہ کہہ کر پردہ سرکا دیا:’’موت بھی خاموشی کا دوسرا نام ہے‘‘۔اُس زمانے میں جب ہمیش جی کو ان کے اپنے شہر میں کوئی عزت و شہرت حاصل نہ تھی، ہندوستان سے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ آئے تو ہر ایک سے احمد ہمیش کی بابت پوچھتے پھرے، مگر اہلِ ادب نے انھیں پھر بھی مان کے نہ دیا۔ ڈاکٹر نارنگ نے دِلّی میں عالمی افسانہ سیمینار کیا تو پاکستان سے تین ادیبوں کو مدعو کیا۔ انتظار حسین، ڈاکٹر وزیر آغا اور احمد ہمیش۔ میں نے اس سیمینار کی ایک تصویر دیکھی جس میں ڈاکٹر وزیر آغاز کے پہلو میں ہمیش جی بیٹھے ہیں مگر ڈاکٹر صاحب نے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف پھیر رکھا ہے، بیزاری کے تاثرات چہرے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس سیمینار میں ہمیش جی کی ملاقات قرۃ العین حیدر سے بھی ہوئی۔ پوچھا: ’’کیسی لگیں؟‘‘اپنی مخصوص گمبھیرتا سے فرمایا: ’’کچھ ٹھیک سے نہیں کہہ سکتا۔ بعد میں وہ آم بہت یاد آیا جو درخت کی شاخ ہی پر سوکھ گیا ہو‘‘۔ عینی کی فنی عظمت اپنے دل پر نقش تھی، اس لیے کہتا تو کیا کہتا! چپ رہا۔ بہت دنوں تک اکیلا رہنے اور کنوارپن کی زندگی گزارنے کے بعد ہمیش جی نے بیاہ رچا لیا۔ کالج میں ہمارے انگریزی کے استاد تھے شاہد اختر صاحب، بہت اچھے شاعر اور نستعلیق سی شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی ہمشیرہ سے ہمیش جی کی شادی ہوئی۔ شاہد اختر صاحب ساری زندگی کنوارے ہی رہے، اور یوں ہی بن بیاہے دنیا سے رخصت ہوئے۔ سالے اور بہنوئی ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ہمیش جی کی بیٹی ہوئی تو محمود کنور نے اس کا نام حضرت رابعہ بصری کی نسبت سے رابعہ رکھا۔ مہنگائی جیسے جیسے آسمان سے باتیں کرتی گئی، ہمیش جی کو زندگی کا بوجھ اٹھانا محال ہوتا گیا۔ بچے پیدا ہوتے گئے، ان کی لکھائی پڑھائی، بیماری دکھ، دوسری ذمہ داریاں… چناں چہ ادب سے ان کی توجہ ہٹی تو نہیں لیکن لکھنے کی رفتار سست پڑتی گئی۔ بہت مدت بعد انھوں نے ایک کہانی لکھی ’’کہانی مجھے لکھتی ہے‘‘۔ اس کہانی کو وہ بہت ڈرامائی انداز میں سناتے تھے، اس طرح جیسے ڈرامہ بول رہے ہوں۔ ہاں انھوں نے ایک ڈرامہ بھی لکھا تھا جو ان کی موت کے بعد ناپا(NAPA) کے اسٹیج پر کھیلا گیا۔ میں نے بہ طورِ خاص جاکر یہ ڈرامہ دیکھا جو تجرباتی اور پُرتاثیر تھا۔ ایک کتاب بھی کہانیوں کی مرتب کرکے انھوں نے چھپوائی ’’عصرِ حاضر کی بہترین کہانیاں‘‘۔ اس میں ان کی مشہور کہانی ’’مکھی‘‘ بھی شامل تھی۔ ان سے مراسمِ محبتانہ استوار کرنے کا ایک فائدہ مجھے بھی ہوا کہ ازراہِ عنایت انھوں نے اس خاکسار کی ایک کہانی کو بھی شرفِ شمولیت بخشا۔ شمولیت کا بہ ظاہر سبب یہ بھی تھا کہ یہ کہانی معاشی بدحالی کے شکار ان سچے ادیبوں کی بابت تھی جنہیں ادبی دنیا کی بے التفاتی کا سامنا تھا۔ کہانی کے ایک کردار میں ہمیش جی کی زندگی اور ان کے احساسات جھلکتے تھے۔ ہمیش جی نے ادب میں اپنی اہمیت منوانے کے بعد میں بہت جتن کیے۔ ایک ادبی رسالہ بھی نکالا۔ اپنی کہانیوں کا مجموعہ بھی شائع کیا۔ طباعت و اشاعت کی طرف بھی آئے اور سارہ شگفتہ کی نثری نظموں کا مجموعہ ’’آنکھیں‘‘ چھاپا۔ لیکن سب کوششیں ناکام و ناتمام ہی رہیں۔ معاش نے انھیں ایسی مار ماری کہ دنیاوی طور پر بھی ناکام رہے، ادب میں بھی نام نہ کما سکے۔ 2010ء میں آرٹس کونسل نے عالمی اردو کانفرنس منعقد کی جس میں انھیں مدعو نہیں کیاگیا۔ اس سے دل برداشتہ ہوکر انھوں نے ایک شکایتی خط کراچی کے ایک ادبی رسالے میں چھپوایا۔ اس خط میں انھوں نے آرٹس کونسل کے منتظمین سے استدعا کی کہ ’’حقیقی اہمیتوں کو قائم کیا جائے، یعنی قائم بالذات کی صورت جو شخصیتیں ہر طرح سے اہل ہیں، ان کا احیا کیا جائے، اس انتہا تک کہ ان کو غاصبین پر غالب کردیا جائے‘‘۔ غالباً ’’غاصبین‘‘ سے ان کی مراد وہ عناصر تھے جو غیر ادبی ہتھکنڈوں سے ادبی سماجیات پر قابض ہوگئے تھے۔ اس خط میں انھوں نے وہ نام بھی گنوائے تھے جنہیں کانفرنس میں نظر انداز کردیا گیا تھا۔ خط میں انھوں نے اپنی اس نظم کا حوالہ بھی دیا تھا: ذرا دیر کی مہلت دے دودنیا کا نظام بدل دوںگایہ دنیا صرف مجھ پرنہیںہر اُس انسان پر بھاری ہےجو صرف جینے کے دوش میں جی رہا ہےاس کے باوجود میں اس امر پر مُصر ہوںکہ اندھیرے کو ہٹائو اور روشنی کا اقتدارقائم کروشاعر بے چارہ خواب دیکھنے اور روشنی کے اقتدار کو قائم کرنے کے دعوے کرنے کے سوا کر بھی کیا سکتا ہے! یہ خط بھی رائیگاں گیا۔ آرٹس کونسل اور لٹریچر فیسٹیول کے میلے آج بھی ان ہی شاعروں اور ادیبوں کی رونق سے آباد ہیں جن پر زندگی ان کی عقل مندی اور حقیقت پسندی سے مہربان ہے۔ احمد ہمیش، محمود کنور، یہاں تک کہ قمر جمیل جیسے ادب پر اپنی زندگیاں نچھاور کردینے اور عوض میں کچھ نہ چاہنے والوں کو کون پوچھتا ہے! ادب لکھنے لکھانے اور ادبی دنیا میں نام کمانے اور مقام بنانے، دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں۔ بے حسی، بیگانگی اور ادبی بددیانتی کے ان رویوں کے قلق پالنے کا فائدہ بھی کیا ہے! سیاست کی طرح ادب میں بھی کامیابی دولت اور سماجی مرتبے کی متقاضی ہے۔ جو اس حقیقت سے آگاہ ہیں، انھیں زندگی اور ادب سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کہ انھوں نے اپنے ادبی معاملات ان ہی سماجی حقیقتوں پر استوار کیے ہیں اور بہ ظاہر کامیاب ہی ہیں۔ ہاں مگر ہمیش جی اور ایسے بہت سے ادیبوں کی حالتِ زار پر پہلے طیش آتا تھا، اب نہیں آتا، اس لیے کہ دنیا اور دنیا میں زندگی کرنے کے معاملات آدمی پر کھل جائیں تو پھر کہاں کا غصہ اور کیسا طیش! وہ آخری شام جب کسی ادبی تقریب میں ہمیش جی سے آخری ملاقات ہوئی، وہ ہال کے باہر برآمدے میں کھڑے اپنی عادت کے مطابق خلائوں میں گھور رہے تھے۔ میں نے قریب پہنچ کر انھیں سلام کیا۔ انھوں نے سر گھما کرمجھے دیکھا اور پھر اسی کیفیت میں چلے گئے۔ اپنی گمبھیر آواز میں پوچھا ’’کیسے ہو؟‘‘ میں نے اثبات میں سر ہلایا، پھر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر عرض کیا: ’’ ہمیش جی! آپ کی رنگت ماند پڑ گئی ہے مگر آپ آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے سعود آباد میںآپ کو دیکھا کرتا تھا۔‘‘’’اچھا‘‘ انھوں نے زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ کہا: ’’زندگی کیا کرتی ہے آدمی کے ساتھ کوئی کیا بتائے۔‘‘’’خوش تو ہیں ناں؟‘‘ میں نے پوچھا’’زندگی سے پوچھو، کیا وہ مجھ سے خوش ہے؟‘‘یہ آخری فقرہ، آخری سوال جو ہم نہیں کرتے، اس کے بعد ان سے پھر ملنا نہ ہوسکا۔ زندگی ہمیش جی سے خوش تھی، ناراض تھی ، دکھی تھی، کچھ بھی تھی، مگر اس نے انہیں جینے کی اور مہلت نہ دی ۔ دے بھی دیتی تو کیا فرق پڑ جانا تھا! ہاں مگر یہ سوچ کر غمزدہ ہوجاتا ہوں کہ ایسا بدنصیب شاعر اور کہانی کار شاید دنیا میں پھر نہ آسکے۔