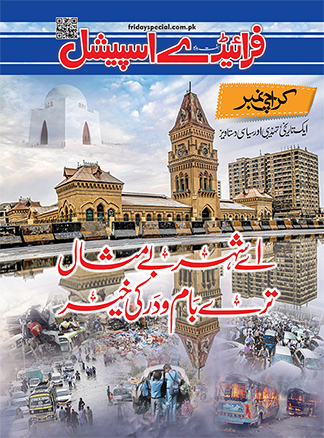عربی کے بعد علوم اسلامیہ پر سب سے زیادہ کام اردو میں ہوا ہے۔ پچھلے دو سو برس سے مستقل تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ عربی و فارسی سے تراث کی اہم ترین کتب اور انگریزی میں اسلام اور مسلم تہذیب سے متعلق تحقیقی کام کو اردو قالب میں ڈھالنے کا جو سلسلہ جاری ہے، اس کی بدولت بلاشبہ اب اردو علوم اسلامیہ کے حوالے سے عربی کے بعد اہم ترین زبان بن چکی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک تازہ اضافہ ترکیہ کے فاضل محقق مرحوم ڈاکٹر محمد فواد سزگین صاحب کے پی ایچ ڈی مقالے کا براہِ راست ترکی زبان سے اردو ترجمہ ہے۔ یہ کارنامہ سمندری فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر خالد ظفر اللہ نے سر انجام دیا ہے۔ یہ اس نادر تحقیق کا کسی بھی زبان میں پہلا ترجمہ ہے اور اس باب میں اردو کو عربی پر بھی سبقت حاصل ہوگئی ہے۔ اس کاوش کا عنوان ’’امام و صحیح بخاری کے مآخذ: ناقدانہ جائزہ‘‘ رکھا گیا ہے۔
ڈاکٹر سزگین کے مقالے کا عنوان ’’بخاری کے مآخذ کی تحقیق‘‘ ہے جس کی تکمیل پر انہوں نے 1954ء میں استنبول یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں انقرہ یونیورسٹی میں استاد کے طور پر تعیناتی کے دوران 1956ء میں اسے انقرہ یونیورسٹی سے ہی شائع کروایا۔ اس اولین طبع کی پی ڈی ایف کاپی انقرہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے بآسانی حاصل کی جا سکتی ہیُ لیکن مقالہ ترکی زبان میں ہونے کی وجہ سے کماحقہٗ استفادہ نہیں ہوسکا۔
ابتدا میں فاضل مترجم و ناقد ڈاکٹر خالد ظفر اللہ نے اس کام کے حوالے سے تین دہائیوں پر مشتمل اپنی سرگزشت بیان کی ہے کہ کیسے ترکیہ میں پی ایچ ڈی کے طالب علم کے طور پر ان کے ایک ہم سبق کی دی ہوئی فوٹو کاپی سے اس علمی سفر کا آغاز ہوا اور پھر یہ دل چسپی کبھی کم نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی مترجم نے اپنے کام کی کامل نوعیت واضح کی ہے کہ انہوں نے ترجمے سے بڑھ کر سزگین صاحب کی تحقیق کا ناقدانہ جائزہ بھی لیا ہے اور جہاں تحقیق میں کچھ سقم معلوم ہوا اُسے بھی رفع کرنے کی کوشش کی ہے۔ تسامحات کو رفع کرنے اور خصوصاً ضمیمہ جات میں موجود قیمتی معلومات کی تکمیل و تصحیح میں جن کتب سے استفادہ کیا گیا ہے اُن کا تعارف اور اس کام کے حوالے سے اُن کے کارآمد ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ یوں دیگر کئی علمی کاموں کا مختصر احوال بھی شاملِ کتاب ہے۔
فاضل مترجم (اگرچہ یہ کام ترجمے سے کہیں بڑھ کر ہے لیکن سہولت کے لیے ہم ڈاکٹر خالد صاحب کے لیے مترجم کا ہی لفظ استعمال کریں گے) نے ڈاکٹر سزگین کا مختصر شخصی تعارف پیش کیا ہے جس میں اُن کی ابتدائی زندگی اور علمی سفر و کارناموں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر سزگین کی ذات اور کام کے حوالے سے کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر سِزگین کو غیر مسلم مستشرق سمجھے جانے کی افسوسناک غلطی کے بیان کے ساتھ اُن کے نام کے صحیح تلفظ کی وضاحت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے مآخذ کے حوالے سے اُن کی کتاب کے بارے میں غلط فہمیوں کو بھی دور کیا گیا ہے، مثلاً یہ کہ مقالہ اصلاً انگریزی میں ہے یا جرمنی میں قیام کے دوران لکھا گیا، یا یہ کہ اس کا عربی ترجمہ ہوچکا ہے۔
اس کے بعد فاضل مصنف (ڈاکٹر سزگین) کا مقدمہ ہے جس میں کتاب کے محتویات کا مختصر بیان ہے۔ ڈاکٹر سزگین کی فرمائش پر اُن کے ایک دوست مارٹن ڈِکسن نے ان کے مقدمے کا انگریزی ترجمہ کیا تھا۔ یہ انگریزی ترجمہ زیرِ نظر کام میں بھی شامل کردیا گیا ہے۔
کتاب کا بنیادی متن تین ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں حدیث کے ابتدائی تحریری مآخذ کا ذکر ہے۔ اس تناظر میں تحملِ حدیث کے صیغوں (یعنی حدثنا، اخبرنا، وغیرہ جیسے الفاظ) کا تعارف اور استعمال کا محل اور مصنف کے اس دعوے کہ امام بخاری نے اپنے سے پہلے کے تحریری مجموعہ ہائے حدیث سے استفادہ کیا ہے، کے درمیان تعلق کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فاضل مصنف نے تحملِ حدیث سے متعلق مستعمل الفاظ کے بارے میں متقدمین کے طرز عمل کو اس طرح واضح کیا ہے کہ روایتِ حدیث کے الفاظ کی موجودگی اور تحریری مآخذ سے استفادے کے دعوے میں تعارض ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً وہ متقدمین سے منقول اقوال کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں کہ روایت میں ’’اخبرنا‘‘ وغیرہ کا استعمال مناولہ یا مکاتبت کی صورت میں بھی روا رکھا جاتا رہا (ص 101) اور کئی متقدمین ان صیغوں میں وہ فرق نہیں کرتے تھے جو متاخرین نے ان کے حوالے سے عمومی طور پر بیان کیا ہے (ص 97، 101)۔ اس اصولی قضیے کو حل کرتے ہوئے وہ صحیح بخاری میں قدیم تر کتب سے اخذ کو شارحین کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ مثلاً کتاب العِلم میں امام بخاری کے استاد حُمیدی کی کتاب النوادر سے استفادہ کرنا۔ حافظ ابن حجر کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں (ص 96-97، 155) اور لکھتے ہیں کہ امام بخاری کا محمد بن بشار سے بطریق مکاتبت روایت کرنا (حدیث 6673) بھی تسلیم کیا گیا ہے (ص 98، 99)۔ اسی طرح ابن حجر ہی کے حوالے سے مسند اسحاق بن راہویہ سے روایت کی مثال بھی پیش کرتے ہیں (ص 129)۔ امام بخاری کے اہلِ شام کی کتابوں پر اعتماد کرنے کی وجہ سے حرفِ تنقید بنائے جانے کی روایت کو فاضل ڈاکٹر سزگین نے ان کے تحریری مآخذ سے استفادے کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے (ص 130)، جو ان کی دقّتِ نظری اور قوتِ استدلال کا مظہر ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت میں امام بخاری ایک شیخ کی کتاب میں بیاض (خالی جگہ) کا ذکر کرتے ہیں (حدیث 5990) جس کی مصنف نے خوب نشاندہی کی ہے (ص 131، 132)۔ اسی طرح وہ امام بخاری کے موطأ کی روایت التنیسی سے اخذ و نقل کو امام زُرقانی کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں (ص132)۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ امام بخاری کی امام مالک سے ایک معلّق روایت ابن عبدالبر نے ابن وہب کی روایت موطأ کے نسخے سے نقل کی ہے (ص 172)۔ البتہ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں امام مالک سے مروی تمام روایات کا موطأ سے نقل ہونے کے مقابلے میں بعض اوقات موطأ سے براہِ راست نقل اور زیادہ تر موطأ سے استفادے کی بنیاد پر لکھی جانے والی دیگر شیوخ کی کتب سے مراجعت کا احتمال زیادہ مناسب ہے (ص140)۔ تحریری مآخذ سے نقل کرنے کے باب میں امام بخاری کے منفرد ہونے کے تاثر کو زائل کرنے کے لیے مصنف اسی سیاق میں امام مسلم کا اپنی صحیح میں تحریری مآخذ سے استفادہ کرنے کو بھی بیان کرتے ہیں (ص129، 132) اور یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ امام ابودائود اور ان سے قبل امام شافعی کا تحریری مآخذ سے نقل کرنا تو مستشرقین نے بھی تسلیم کیا ہے (ص 122)۔
کتاب کا دوسرا باب ’’صحیح بخاری میں تفسیر ِقرآن کے مآخذ‘‘ کے عنوان سے ہے۔ اس میں صحیح بخاری میں مختلف مقامات پر مذکور تفسیری اقوال کی اصل کے بارے میں تحقیق پیش کی گئی ہے۔ فاضل مصنف نے صراحت کی ہے کہ اگرچہ یہ مواد صحیح بخاری میں جابجا موجود ہے لیکن ان کی تحقیق کا محور کتاب التفسیر میں منقول اقوال ہی ہوں گے (ص 195)۔ باب کے شروع میں مصنف نے صحیح بخاری کے پہلے سے موجود تحریری ذخیرہ ہائے علم کا خلاصہ ہونے کا نظریہ دہرایا ہے، اور تمہیداً یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ امام بخاری سے پہلے کے مؤلفین کتبِ سُنن نے اپنی کتب میں تفسیر کا باب قائم نہیں کیا (ص 195) اور اس حوالے سے بخاری اپنے متقدمین سے ایک امتیازی وصف رکھتے ہیں بلکہ اپنی تالیف میں موجود تفسیری و لغوی مواد کی کیفیت و ماہیت کے اعتبار سے بعد کے کاموں سے بھی صحیح بخاری مختلف ہے۔ صحابہ، تابعین اور بعد کے لوگوں سے منسوب تفسیری اقوال کو الگ الگ شمار کیا گیا ہے اور اس اہم امر کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ان اقوال کے لیے امام بخاری نے کوئی سند ذکر نہیں کی اگرچہ ان میں بہت سے اقوال کو آپ سے پہلے امام عبدالرزاق صنعانی اور آپ کے بعد امام طبری اور ابن ابی حاتم نے انہی حضرات سے با سند روایت کیا ہے۔ بلکہ ان اقوال کو مسند نقل کرنے والے بعض ذرائع تک امام بخاری کی رسائی کے شواہد بھی موجود ہیں۔ لہٰذا مصنف کا خیال ہے کہ امام موصوف نے ایسا قصداً کیا ہے۔ (ص 196-201)
اس باب میں ابوعبیدہ اور فراء کے تفسیری اور لغوی اقوال کو الگ الگ زیر بحث لایا گیا ہے۔ اول تو یہ بتایا گیا ہے کہ ابوعبیدہ جن کا اصل نام مَعمر تھا ان کو صحیح بخاری میں صرف معمر کہہ کر ذکر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی درست شناخت ایک عرصi تک معروف طور پر متعین ہی نہیں کی جا سکی۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ابوعبیدہ کا کام دیکھنے سے قبل وہ یہی سمجھتے تھے کہ معمر سے مراد معمر بن راشد ہیں۔ اگرچہ بعد میں ان کو اس حوالے سے ابن التین اور نووی کی شہادتیں بھی میسر آ گئیں (ص 214-216)۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ابوعبیدہ کی مجاز القرآن سے نقل میں کوئی خاص ترتیب معلوم نہیں ہوتی۔ کئی مقامات پر غیر ضروری اور غیر متعلقہ اقباسات نقل کردیے گئے ہیں (ص 219-221)، کہیں بلا ضرورت اقتباسات کی تکرار بھی ہے اور تفسیر قرآن سے متعلقہ کچھ حصّے تو مصحف کی ترتیب کے مطابق بھی نہیں (ص 222-223)۔ اس صورتِ حال نے بعض شارحین کو پریشان بھی کیا ہے۔ ساتھ ہی وہ اس بے ترتیبی پر شارحین کے مختلف رویّوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ابن حجر کہیں تو اس کی توجیہ کرتے نظر آتے ہیں اور کہیں اس کی ذمہ داری ناسخین پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قسطلانی بھی عقیدت میں اسے عمیق امر جانتے ہیں البتہ کرمانی اس کو لایعنی کہنے کی جرأت رکھتے ہیں۔ عینی کی بھی ایسی ہی رائے ہے گو وہ ان کی افادیت کے منکر نہیں (ص 222-225، 241)۔ بعض مقامات پر ابن حجر بھی اقتباسات کی مناسبت کی بابت کسی تاویل و توجیہ سے عاجز دکھتے ہیں تو مصنف اس سے اپنے موقف کو تقویت پاتا محسوس کرتے ہیں کہ یہ سب امام بخاری نے دیگر کتب کے اسلوب سے متاثر ہوکر کیا ہے اور اس حوالے سے متاخرین کی بیان کردہ شرائط محض خیالی ہیں۔ (ص 222)
فراء کی شناخت بھی ان کا نام صرف یحییٰ لکھے جانے کی وجہ سے مستور رہی، اور شروع کے شارحین جیسے خطابی وغیرہ نے اس سے تعرض ہی نہیں کیا۔ یہاں بھی ابن حجر نے ہی ان کا فراء ہونا واضح کیا۔ کرمانی، یحییٰ کے نام سے منقول اقوال کو یحییٰ بن سعید سے منسوب کرتے رہے۔ علامہ عینی نے بھی ان کا فراء ہونا دیر سے ہی قبول کیا (ص 237-238)۔ اس کے بعد مصنف نے فراء کے اقوال کی مناسبتوں پر بات کی ہے۔ یوں اس باب میں صحیح بخاری میں منتشر ان اقتباسات کے امام بخاری سے قبل کے دو تحریری مآخذ کی نشاندہی شارحین کے اقوال کے حوالے سے ثابت کی گئی ہے۔ ان اقتباسات کی نشاندہی ضمیمہ سوم و چہارم میں کی گئی ہے۔ (ص 709-772)
کتاب کے تیسرے باب کا عنوان ہے ’’الجامع الصحیح کی روایات‘‘۔ اس باب میں فاضل مصنف نے صحیح بخاری کی مختلف روایات کی تاریخ، ان کے باہم تقابل اور اس سے متعلقہ امور پر بحث کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک ہزار راویوں میں سے صرف پانچ کے نام محفوظ ہیں اور اُن میں سے بھی دو کی روایت کا متداول ہونا تاریخی طور پر ثابت ہے۔ یہ فِرَبری اور نَسَفی کی روایات ہیں۔ چھٹی صدی ہجری کے بعد سے البتہ صرف فربری کی روایت ہی معروف رہی ہے (ص 251)۔ نسفی کی روایت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امام بخاری کے بعد دو صدیوں تک تو معروف رہی اور امام خطابی نے اپنی شرح بھی اسی روایت کے متن کو سامنے رکھ کر لکھی، لیکن بعد میں پس منظر میں چلی گئی۔ فربری کی روایت کو نسفی پر ترجیح حاصل ہونے کے کچھ ممکنہ اسباب کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ صحیح بخاری کے آخر سے کچھ حصے کا براہ ِراست امام بخاری سے سماع کا موقع نسفی صاحب کو غالباً نہیں مل سکا، دوسری وجہ راویوں کی تعداد کا فرق رہی کہ فربری کی روایت کو 9 راوی ملے اور نسفی کی روایت کو صرف 2۔ پھر نسفی کی روایت میں کچھ غیر محفوظ اضافوں کا اندیشہ بھی شاید اس کی وجہ بنا (ص 258-259)۔ لیکن بعض پہلو ایسے بھی تھے جن میں نسفی کی روایت فربری سے بہتر سمجھی گئی جیسے متن کی اہم تفصیلات کا مکمل طور پر محفوظ ہونا۔ اسی طرح کچھ لغوی مواد کا صرف روایت نسفی میں ہی پایا جانا، اور اس میں تکرار کا نہ ہونا بھی روایت نسفی کے اوصاف میں شمار کیا گیا ہے (ص 259-262)۔ ان امور اور فربری کی بعض ذیلی روایات کا تذکرہ کرنے کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ مِن جملہ نسفی کی روایت فربری کی روایت سے بہتر گردانی گئی ہے (ص 275)۔ اس کے بعد فاضل مصنف نے صحیح بخاری میں کاتبین کے تصرف پر بات کی ہے کہ ایسا ہو بھی تو زیادہ اہم نہیں ہے جیسے کسی کا مبہم نام ’’محمد‘‘ کی جگہ (التباس کو رفع کرنے کی نیت سے) ’’نفیلی‘‘ لکھ دینا (ص 277)۔ شروطِ بخاری کے حوالے سے کتب کا ذکر کرتے ہیں اور مثال سے واضح کرتے ہیں کہ اس باب میں بعض غیر حقیقی باتیں بھی کی گئی ہیں جن کی غلطی ابن حجر و دیگر شارحین نے بیان کی ہے۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ صحیح بخاری اور دیگر کتب کا باقاعدہ مقدمہ وغیرہ نہیں ہے لہٰذا اس باب میں جو کہا گیا ہے وہ ان ائمہ سے منقول نہیں۔ امام مسلم کی کتاب کا مقدمہ ہے لیکن اس میں بھی ان امور کی وضاحت نہیں (ص 280-281)۔ آخر میں صحیح بخاری پر ہونے والی تنقیدات کا ذکر کیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ صحیح بخاری کو جو مقام حاصل ہے یہ صدیوں کے نقد اور بحث و تمحیص کا نتیجہ ہے، اور امت کے اجماع نے صحیح بخاری کو بلند مقام پر فائز کیا ہے۔ (ص 285-288)
ڈاکٹر سزگین کے کام کا معرکہ آرا ہونا ان تین ابواب میں محقَّق نظریات سے ظاہر ہے تو چوتھے باب میں دیے گئے ضمیمہ جات میں دی گئی معلومات سے اظہر ہے۔ پہلے ضمیمے میں شیوخ بخاری اور شیوخِ شیوخ بخاری کے بارے میں انتہائی اہم تفصیلات نقشوں کی صورت میں دی گئی ہیں۔ کمپیوٹر اور فہارس کے دور سے قبل اس کام کے سرانجام دینے میں جو محنت اور ہمّت درکار تھی وہ فاضل مصنف کے عمیق مطالعہ صحیح بخاری پر شاہد ہے۔
دوسرے ضمیمے میں مصنف نے صحیح بخاری میں امام مالک کی مرویات کی موطأ میں نشاندہی کی ہے۔ یقیناً یہ بھی ایک دلچسپ اور اہم موازنہ ہے اور پہلے باب میں درج مصنف کے نظریے کا گویا بیّن ثبوت ہے۔ تیسرا اور چوتھا ضمیمہ صحیح بخاری میں بالترتیب ابوعبیدہ کی مجاز القرآن اور فراء کی معانی القرآن کے اقتباسات کی نشاندہی کے لیے مختص ہیں۔ یہ دوسرے باب کے تکملہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔
ڈاکٹر سزگین کا یہ کہنا درست ہے کہ ان کی تحقیق میں عام خیال سے بہت ہٹ کر نتائج سامنے آئے ہیں اور تین صدیوں تک محض زبانی روایت کے تصور کی قلعی کھل گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ فاضل مصنف نے اس امر کو ثابت کرنے کے لیے روایت سے ہی شواہد اس طرح اکٹھے کردیے ہیں کہ امام بخاری کا ماقبل کے تحریری مآخذ سے استفادے کا مطلقاً انکار ممکن نہیں رہا۔ البتہ فاضل مصنف کا یہ دعویٰ کہ ابتدا سے انتہا تک‘‘ صحیح بخاری تحریری مجموعہ ہائے حدیث سے ہی مرتب کی گئی تھی (ص 121) نہ صرف یہ کہ ابھی تشنہ تحقیق ہے بلکہ بہت حد تک مستعبد بھی ہے۔ اس درجہ عمومیت اور قطعیت کے ساتھ اس نظریے کا ثابت ہونا شاید ممکن ہی نہیں۔ مصنف کا فرمانا کہ مثلاً امام مالک کی مرویات کے سلسلے میں امام بخاری نے ہمیشہ موطأ سے براہِ راست استفادہ نہیں کیا ہوگا بلکہ یہ روایات انہوں نے اپنے اساتذہ/شیوخ کے تحریری مجموعوں سے لی ہوں گی، کچھ مبنی بر تَحکم محسوس ہوتا ہے۔ ایسے تمام غیر معروف تحریری مجموعات کا تاریخی ثبوت سامنے آنا بظاہر ممکن نہیں اور نہ ہی امام بخاری کا ایسا کوئی قول ذکر کیا گیا ہے، اس لیے زیادہ مناسب احتمال یہی معلوم ہوتا ہے کہ زبانی روایت کے ساتھ ساتھ اصولِ روایت کے تحت موطأ امام مالک سمیت تحریری مآخذ سے استفادہ کیا گیا۔ بہر صورت فاضل مصنف کی تحقیق مستشرقین اور منکرین و مشککینِ حدیث کے مزعومات کا رد کرتی ہے۔
ترجمے کا کام ہی کچھ کم نہ تھا کہ ڈاکٹر خالد ظفر نے اس پر تحقیق و تعلیق سے امّت کی طرف سے ڈاکٹر سزگین کی تحقیق سے دہائیوں تک عدم اعتناء کا گویا کفارہ ادا کردیا ہے۔ فاضل مصنف کی ذکر کردہ روایات اوردیگر حوالہ جات کی تحقیق اور محولہ کتب سے اصل اقتباسات کو نقل کرنا ازسرنو تحقیق سے کم نہیں۔ مزید یہ کہ فاضل مترجم نے صرف ترجمہ اور اقتباسات کی نقل سے بڑھ کر نقد و نظر کا فریضہ بھی سر انجام دیا ہے۔ جہاں کہیں انہیں محسوس ہوا کہ اصل اقتباس اور فاضل مصنف کے بیان میں کچھ فرق ہے آپ نے اس کی بلا تردد نشاندہی کی ہے۔ (مثلاً ص 93، 200)
اسی طرح متن کی بعض اغلاط کی بھی فاضل مترجم نے نشاندہی کی ہے (مثلاً ص 91 حاشیہ 1، ص 154، ص 199، ص 213 حاشیہ 4، ص 216-217 حاشیہ6، ص 221 حاشیہ3) متعدد مقامات پر مترجم نے اہم امور کی وضاحت اور معلومات کا خود سے بھی حاشیے میں اضافہ کیا ہے، البتہ رموز کی مدد سے ان اضافوں کو مصنف کے حواشی سے ممیز رکھا گیا ہے (ص82-83، 90، 106، 121، 146-147، 149، 175 وغیرہ)۔
تاہم بعض مقامات پر مصنف پر مترجم کا تعاقب محل نظر بھی ہے۔ مقدمے اور پہلے باب کے آخر میں امام بخاری کے اسناد وروایت کی اہمیت کو کم کرنے کے حوالے سے مصنف کے قول کو سمجھنے میں مزید تامل کیا جانا چاہیے تھا (ص 36-37 ، 191) باب اول کے جمیع مشمولات کو سامنے رکھا جائے تو مذکورہ مقامات پر مصنف کے الفاظ سے یہی مفہوم ملتا ہے کہ تحریری استفادہ کو شامل طریقہ ہائے تحملِ روایت کو بَرت کر امام بخاری نے محض زبانی روایت کی اہمیت کو کلّی انحصار کے اعتبار سے کم کردیا تھا۔ اور آپ اتنے بڑے پیمانے پر یہ کام کرنے والے پہلی شخصیت تھے۔ اس امر کے محقق ہونے پر تو دو رائے ہوسکتی ہیں لیکن یہ کہنا کہ مصنف کی مراد مطلقاً روایت واسناد کی اہمیت کو کم کرنا تھا، درست نہیں۔
تدوین حدیث سے متعلق امام زہری کی مساعی کے ذکر میں متن کا ترجمہ یہ تاثر دیتا ہے کہ مصنف کے خیال میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو خلافت سے متعلق احادیث جمع کرنے کا کہا تھا۔ چنانچہ مترجم اس پر معترض ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مقصود عموماً احادیث کی تدوین تھا، نہ کہ خاص خلافت سے متعلقہ روایات کو جمع کرنا (ص83-84)۔ البتہ اصل ترکی عبارت میں مصنف کا کہنا ہے کہ تدوین حدیث کا آغاز جس دور میں ہوا اُس وقت عمر بن عبدالعزیز خلافت کے منصب پر فائز تھے۔ لہٰذا مترجم کا اعتراض درست نہیں اور مصنف کی اصل عبارت کا ترجمہ دُرستی چاہتا ہے۔ ایک مقام پر فتح الباری سے منقول ایک عبارت میں ترکیب ’‘’شقیق الراوی‘‘ سے مراد راوی حدیث شقیق (بن سلمہ) ہیں۔ مصنف نے ترکی ترجمہ میں بھی اس کو ایسے ہی لکھا ہے لیکن مترجم اس کو ’’راوی کا بھائی‘‘ سمجھے ہیں (ص 129)۔ ڈاکٹر سزگین صاحب کے مقدمے کا انگریزی ترجمہ شامل کتاب تو کیا گیا ہے (ص 39 – 45) لیکن محض نقل کے اس کام میں بھی کمپوزنگ کی بہت زیادہ غلطیاں ہوگئی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کمپوزر اور ناشر نے اس کو ایک نظر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ مصنف نے مقدمے میں صحیح بخاری کے روایتِ فربری اور روایتِ نسفی کے تقابل میں جو لکھا ہے اس کا اردو اور انگریزی ترجمہ بالکل مختلف ہے۔ اردو ترجمے کے مطابق فربری کی روایت کو روایتِ نسفی پر تاریخی ترجیح کے متعدد اسباب تھے (ص 37) جبکہ انگریزی ترجمے کی رو سے نسفی کی روایت کے مقابلے میں روایتِ فربری کی ترجیح نامناسب (ill-chosen) تھی۔ کتاب کے تیسرے باب میں درج تفصیلات کی روشنی میں انگریزی ترجمہ مصنف کے حاصلِ تحقیق سے زیادہ ہم آہنگ معلوم ہوتا ہے۔
ترجمہ ایک مشکل فن ہے اور ترجمے کی عبارت میں کچھ مشکل کا آنا گویا ناگزیر ہوتا ہے۔ اس کتاب میں بھی کچھ عبارات نظرِ ثانی کی متقاضی ہیں۔ اصل زبان میں ترکیب کا اسلوب کچھ بھی ہو ’’عادت کے مالک‘‘ (ص 81) کی جگہ ’’عادی‘‘ کا استعمال زیادہ مناسب تھا۔ ص 109 پر ابوسلمہ التبودکی اور ابن معین کے حوالے سے عبارت غیر واضح ہے۔ بعض جگہ املا کی معمولی غلطیاں ہیں۔ امید ہے کہ آئندہ طباعت میں ان کو درست کرلیا جائے گا۔
پہلے ضمیمے میں شیوخِ بخاری سے متعلق معلومات انتہائی اہم ہیں۔ مترجم نے مصنف کی تحقیق میں واقع متعدد تسامحات کی اصلاح کی ہے جو اس باب میں ان کی محنت اور تحقیق پر دلالت کرتی ہے۔ مقدمے میں مترجم نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ شیوخ بخاری پر مستقل کام بھی کررہے ہیں (ص 17)۔ دعا ہے کہ اللہ ان کو اس کام کی جلد تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔
مجموعی طور پر طبع وجلد معیاری ہے۔ ضخامت کے اعتبار سے قیمت بھی زیادہ نہیں۔ کاغذ درمیانہ ہے۔ اس سے بہتر ہوتا تو قیمت بہت گراں ہو سکتی تھی۔ صفحہ نمبر 101اور102کی ترتیب الٹ گئی ہے۔ صفحہ 136-137 پر دی گئی اسناد کے نقشے ایک ہی صفحے پر ہوتے تو سمجھنے میں آسانی رہتی۔
ہر بشری کاوش میں بہتری کی گنجائش تو رہتی ہی ہے لیکن اس کتاب کی اشاعت یقیناً لائقِ ستائش ہے۔ کتبِ حدیث اور علومِ حدیث پر اردو زبان میں کام کرنے والوں کو اس کتاب کے مصنف ومترجم کی اپنے موضوع سے لگن سے راہ لینی چاہیے۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ صحیح بخاری کے تحریری مآخذ اور ان سے متعلق دیگر امور کے حوالے سے مصنف کے نظریات پر تحقیق کو آگے بڑھایا جائے۔ روایتی اور عصری جامعات کے دینی علوم سے وابستہ اہلِ علم کو مترجم کی کوشش سے استفادہ کرتے ہوئے فاضل مصنف کی تحقیق کا تنقیدی نظر سے جائزہ لینا چاہیے۔ اس ضمن میں امام بخاری کے اسلوبِ تالیف وتصنیف اور ان کے شیوخ کے حالات اور ان کے تحریری مجموعات کی موجودگی کے ثبوت یا عدم ثبوت، تحملِ حدیث کے حوالے سے ان کی آراء پر دستیاب معلومات، معلق روایات اور تراجمِ ابواب کے تحت درج لغوی مواد کی اپنے مقامات سے مناسبت اور اس حوالے سے صحیح بخاری کی مختلف روایات میں فرق اور ان کی معنویت کو تحقیق کے میدان کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مترجم کی یہ کوشش امتِ مسلمہ کے سرمایہ افتخار علم حدیث کی اہم ترین کتاب صحیح بخاری پر نئے زاویہ ہائے نگاہ سے تحقیقات کا سبب بنے۔