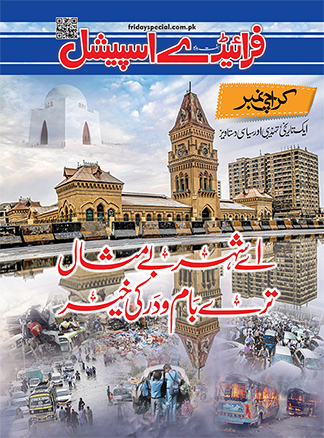آدمی کیسا کٹھور ہے۔ کس چیز کے لیے کیسی نادر زندگی وہ قربان کردیتا ہے۔ تہذیب کی دہلیز پر کتنے سچے لوگ، کتنے سچے زمانے، کتنا اجالا اور کتنی روشنی بھینٹ چڑھا دی جاتی ہے۔ بھولے بسرے زمانے جب جاگ اٹھتے اور ٹلنے سے انکار کردیتے ہیں۔ ماضی نہ مستقبل، وہ ایک ساعت ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ دل اس کی گرفت میں کیسا تڑپ اٹھتا ہے اور تڑپتا رہتا ہے۔ احمد جاوید سے میں نے کہا تھا: اب کی بار صحرا کا قصد ہو تو مجھے ساتھ لے جائیے گا۔ میری کتنی ہی یادیں روہی کے ریگزار سے وابستہ ہیں… وہی احمد جاوید جنہوں نے کہا تھا: کاروبارِ زندگی سے جی چراتے ہیں سبھی جیسے درویشی سے تم، جیسے جہانبانی سے ہم شاعر، ایک روایتی صوفی، میر تقی میر ؔکا معلم اور اقبالیات کا استاد۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ مجھے ساتھ نہ لے گئے۔ دل و دماغ پر جانے کیا گزرتی۔ لوٹ کر آتے تو شہر کی مصنوعی زندگی اور بھی دشوار ہوجاتی، 45 برس میں جس سے آہنگ پیدا نہ ہوسکا۔ رات کا آخری پہر ہے اور اس کا سناٹا۔ چولستان کی گداز خاموشی، ہوٹل کے سجے سنورے وسیع و عریض کمرے میں در آئی ہے۔ اب نیند کہاں کی! آج کی شب پو پھٹے تک جاگنا ہے۔ اس سچّی فطری اور بے ساختہ حیات کا ماتم ہے، ایک بڑے شہر میں، نمود ذات کی بے رحم تمنا کی آرزو پر جو قربان ہوگئی۔ آج میں اندازہ کرسکتا ہوں کہ خواجہ غلام فرید، اس نادرِ روزگار شاعر اور راہِ سلوک کے اس مسافر نے ہمیشہ باقی رہنے والے وہ نغمے کیسے لکھ دیے جو ابدالآباد تک زندہ رہیں گے۔ صحرا سے اس نے محبت کی، جسے چھوڑ کر ہم بھاگ نکلے تھے۔ اقبال یاد آئے۔ اسی شہر لاہور میں خواجہ کو انہوں نے یاد کیا اور یہ کہا تھا: غلام فرید ایسا شاعر جس قوم میں موجود ہو، وہ مجھے کیوں پڑھے گی؟ ہاں، وہ درد اور سوز و گداز سے بُنے گئے مصرعے، فطرت کی گود میں ہمکتی، جیتی، سپنے دیکھتی، صحرائی زندگی کی متحرک تصویریں۔ تاروں کی چھاؤں تلے، سچی محبت کا کبھی نہ ختم ہونے والا فسانہ۔ روشنی کی وہ چھب جب شاہد اور مشہود کے درمیان بس بالشت بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ آسمانِ دنیا کو روشنیوں سے منور کرنے والا خالق، جب ایک ہُوک کی دوری پر ہوتا ہے۔ اقبال کو صحرا کی مادری محبت ایسی مہربان ہَوا کا تجربہ کم تھا مگر وہ اس سے باتیں کیا کرتے:
اے باد بیابانی مجھ کو بھی عنایت ہو
خاموشی و دل سوزی، سرمستی و رعنائی
ہم صحرا کے پڑوسی جانتے ہیں کہ شب کی ہوا میں کیسی تازگی، کتنی گہری پُراسراریت ہوتی ہے۔ چاندنی رات میں اونٹوں کے خاموش قافلے، کبھی کبھار کسی ہرن کا خرام، ایسے میں بانسری کی ایک تان قلب و جگر کو چیرتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ وقت جیسے ٹھیر ہی جاتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی جوان تھے تو کچھ دن اس دیار میں رہے۔ صحرا کے باطن میں انہوں نے جھانک کر نہ دیکھا مگر ستلج اور صحرا کے کنارے پر آباد ایک شہر میں۔ عمر بھر ان دنوں کی یادیں شاعر کے دل میں دمکتی رہیں۔ اس کی میٹھی بولی کی بازگشت ”سائیں! کِن ویندو‘‘… ”سائیں! اِن ویندوں‘‘۔ دستکاریوں کے مراکز میں رنگین پارچوں پر لکھے خواب سجے ہیں، دنیا میں کہیں جن کی کوئی مثال نہیں۔ رنگوں کا ایسا تال میل کہ مصوّر بھی رشک کرے۔ بدروحوں کو بھگانے کے لیے دلہن کے ہاتھ میں ایک چھری ہوتی ہے، رنگین پیرہن جسے ڈھانپ رکھتا ہے۔ اس کا ایک ایک تار ہاتھوں سے بُنا گیا ہے۔ تقریب کے ہنگام دولہا کے ہاتھ میں ایک چھڑی، وہ بھی گل رنگ دھاگوں سے ڈھانپی گئی۔ برسات کے بعد یکایک دور دور تک کھل اٹھنے والے پھول۔ درختوں اور پھولوں ایسے سادہ دل مکین، جن میں سے ایک نے ابھی ابھی یہ کہا ”سائیں، یہ جنگل کہیں جانے بھی نہیں دیتا‘‘۔ پہناوے اور چادریں اور بستر پر بچھانے والی رلّی۔ چہار طرف پھیلی ویرانی میں شوخ رنگوں کی آرزو، دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے۔ شاموں، صبحوں اور راتوں کی خاموشی میں ذاتِ باری تعالیٰ کا جلوہ، جس نے اپنا سچا پیغمبر صحرا میں اتارا تھا: کیا اس نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں، نظر میں، اذانِ سحر میں۔ اس صحرا کے کچھ مکین بھی وہیں سے آئے تھے۔ چار سو برس پہلے جب قحط یا دشمن کی یلغار نے انہیں بے گھر کیا۔ کیا عجب ہے پندرہ سو برس پہلے، یہ کھجور کے درخت بھی، جن کی شاخوں پر بیتے گزرے ہوئے زمانے لکھّے ہیں۔ لودھراں سے ذرا آگے، وہ چھوٹا سا باغ جہاں ہم ایک موڑ مڑتے ہیں۔ آگے بڑھنا مشکل ہوجاتا ہے۔ خواجہ فرید کی کوک سنائی دیتی ہے اور لاہور کا شاعر منیر نیازی یاد آتا ہے :
اکّو کوک فرید دی، سنجے کر گئی بن
اگرچہ وہ دوسرے فرید تھے، خواجہ فریدالدین مسعود گنج شکر، بادشاہ جن کے سامنے جھکا اور اتنا جھکا کہ تاریخ میں امر ہو گیا۔ ایک لشکر جس کے دربار میں اترا اور اس طرح اترا کہ سپاہی صوفی ہوگئے، پورے کا پورا لشکر۔ اس آدمی کا نام غیاث الدین بلبن تھا اور اس نے وہ اعزاز پایا جو کبھی کسی سلطان کو نصیب نہ ہوا تھا۔ بادشاہ کی نور نظر فقیر سے بیاہی گئی۔ ایک اور شاعر تھے، ظہیر کاشمیری۔ کبھی ایک شب روہی میں انہوں نے بسر کی تھی اور دائمی ہوگئی۔ میں سر جھکا لیتا ہوں، 45 برس پہلے کی وہ صبحیں اور شامیں۔ اپنے منفرد لباسوں میں، جب صحرا کی بیٹیاں سرخ مرچ اور ہلدی کی پوٹلیاں بی بی جی کے سامنے ڈھیر کیا کرتیں۔ ”بی بی جی! پسائی میں ایک چھٹانک کم ہوگئی اور ایک چھٹانک سرسوں کا تیل اس میں ڈالا گیا‘‘۔ بچّے حیران ہوا کرتے کہ بازار میں پسے ہوئے مصالحے ارزاں ہیں۔ اتنے سے کام کے لیے دور دراز سے سفر کرکے وہ کیوں آتی ہیں؟ بی بی جی نے سر اٹھا کر دیکھا: کبھی تم جان لو گے کہ محبت بھرے ہاتھوں سے ذائقے سوا ہوجاتے ہیں۔ کم سن بچیوں کو قرآن پڑھاتے ممانی جی متوجہ ہوئیں اور ہمیشہ کی شیریں آواز میں کہا: کیسری! تم مسلمان کیوں نہیں ہوجاتیں؟ کیسری نے مرچوں کی پوٹلیاں اٹھائیں اور دروازے کی اور جاتے یہ کہا: ہم صحرا والے جانتے ہیں کہ سب انسانوں کا ایک ہی رب ہے۔ کچھ اسے رحیم کہتے ہیں، کچھ رام۔ بارش وہی برساتا ہے۔ سانپ کے کاٹے مجروح اسی کے نام سے شفا پاتے ہیں۔ پھر ساربانوں کی صدائیں اور اونٹوں کے گلوں میں بجتی گھنٹی کی آوازیں۔ بہت دور، دریا کنارے سے وہ ایندھن لے کر آتے ہیں۔ سرکنڈوں ایسی جھاڑیاں جو چولہوں میں خوب دھڑا دھڑ جلتی ہیں، جیسے کسی نے ماپ تول کر بنائی ہوں، سوا روپے میں ایک اونٹ کا بوجھ، ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس، کبھی کبھار شربت بھی۔ وہ زندگی کہاں چلی گئی، وہ چاندنی راتیں کیا ہوئیں؟ شاعر نے کہا تھا:
شہر ہیں یا کہ تمدّن کے عقوبت خانے
عمر بھر لوگ چنے رہتے ہیں دیواروں میں
دو ہزار برس پہلے یہ ویرانہ آباد تھا۔ ایک اعتبار سے نصف صدی پہلے بھی جب دنیا بھر سے سیکڑوں اہل ذوق صحرا کی چاندنی راتوں کا قصد کیا کرتے! پھر کیا ہوا؟ پھر شہروں کو برباد کرنے والے تمدن اور سیاست نے ریگ زار کو بھی رفتہ رفتہ برباد کرڈالا۔ آدمی کیسا کٹھور ہے۔ مصنوعی حیات کے لیے زندگی وہ قربان کردیتا ہے۔ تہذیب کی دہلیز پر کتنے سچے لوگ، کتنے سچے زمانے، کتنا اجالا اور کتنی روشنی بھینٹ چڑھا دی جاتی ہے۔
(ہارون رشید۔روزنامہ دنیا۔ پیر 21 فروری 2022ء)