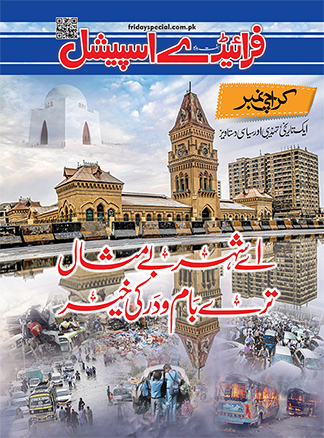ایسا کہاں سے لائوں کہ تجھ سا کہیں جسے
یہ کورونا وائرس کے دنیا پر حملے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک رات موبائل کی گھنٹی بجی۔ اٹھایا تو دوسری طرف پروفیسر عنایت علی خاں تھے۔ فرمایا: ’’ڈاکٹر سہیل انصاری خیرپور یونیورسٹی کے طلبہ کے ساتھ کراچی آرہے ہیں۔ آپ کی یونیورسٹی بھی آئیں گے۔ کیا آپ سے ملاقات کی صورت نکل سکتی ہے؟‘‘
یہ اُن سے آخری ملاقات اور موبائل پہ آخری بار کی گفتگو تھی۔ وہ طلبہ کے ساتھ ہمارے ڈپارٹمنٹ آئے تھے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اب دوبارہ ملنا ملانا نہ ہوسکے گا۔ ان سے جب بھی ملنا ہوا اسی طرح ہوا۔ کوئی نہ کوئی تقریب ملاقات کی جب بھی ہوئی ان ہی کی طرف سے ہوئی۔ جب بھی ملے شگفتہ مزاجی اور بے تکلفی کے ساتھ ملے۔ بزلہ سنجی شاعری ہی میں نہیں، فطری طور پر مزاج میں شامل تھی۔ حلیے بشرے سے قطعی طور پر باشرع، دیکھنے میں دور و قریب سے لگتے ہی نہیں تھے کہ ایسے ہوں گے۔ مگر ایسے ہی تھے۔ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ جن سے مل کر زندگی سے پیار ہوجائے وہ لوگ آپ نے دیکھے نہ ہوں گے مگر ایسے بھی ہیں۔ بزلہ سنجی، ہنسی مذاق اور لطف اندوزی کے ساتھ ساتھ سنجیدگی، گمبھیرتا اور دل سوزی… ان سب کا بڑا دلکش امتزاج تھے۔ ان سے مراسم کو یاد نہیں کتنا زمانہ گزرا۔ برسوں پہلے یاد پڑتا ہے کہ ان کا اسی طرح فون آیا تھا کہ میرے ایک عزیز ہیں وہی ڈاکٹر سہیل انصاری، پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ انھیں اپنی نگرانی میں لے لیں۔ شاید یہ ان سے پہلا رابطہ تھا۔ نام اور کلام سے کون ادب دوست ایسا ہوگا جو ان سے واقف نہ ہوگا! سو میں بھی انھیں جانتا تھا۔ ہماری یونیورسٹی میں انجمنِ اساتذہ نے ایک مشاعرہ کرایا تھا، اس میں آئے تھے اور اپنی ایک نظم سنائی تھی جو اُن دنوں بہت مشہور ہوئی تھی۔ کچھ اس قسم کی ’’ذرا یہ ورلڈ کپ ہولے تو اس کے بعد دیکھیں گے‘‘۔ کرکٹ کا بخار ہماری قوم پر اس طرح طاری ہوجاتا ہے کہ سارے اہم اور ضروری کام اس کھیل کے ماتحت ہوجاتے ہیں، فضا میںکرکٹ کی بو باس اس طرح رچ بس جاتی ہے کہ مجال ہے جو کوئی اور کام اس کے مقابلے میں نگاہوں میں جچتا ہو۔ اس صورتِ حال کی کیا خوب منظرکشی کی تھی انھوں نے اپنی نظم میں۔ اُس روز کیا، تقریباً ہر مشاعرے میں وہی اور ان کا کلام ہی حاصلِ مشاعرہ ہوتا تھا۔ ایک نظم سناتے تو دوسری کی فرمائش ہوتی۔ دوسری کے بعد شور مچتا ایک اور، ایک اور… اور یوں آخر میں انھیں زبردستی خود ہی سامعین کے سامنے سے معذرت کرکے اٹھنا پڑتا تھا کہ بھئی دوسرے شعرا بھی ہیں، ان کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔
ایک مرتبہ کیڈٹ کالج پٹارو میں یومِ اقبال کے موقع پر انھوں نے مجھے مدعو کیا۔ ان کی دعوت پر گیا تو خود بھی وہاں موجود تھے۔ بڑی عزت افزائی ہوئی۔ کالج کے پرنسپل سے متعارف کرایا۔ مہمانوں کا پودا لگانا کالج کی پرانی رسم تھی، سو ان کی موجودگی میں پودا لگانے کی رسم بھی ادا کی۔ اب تو وہ تناور درخت بن گیا ہوگا۔ جب تک وہ رہے اپنے فقروں سے محفل کو زعفران زار بنائے رکھا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ سنجیدہ گفتگو کے ساتھ ساتھ پُرمزاح فقروں کی پھلجڑیاں ان کی طرف سے چھوٹتی رہتی تھیں، دل سوزی بھی بہت تھی۔ قوم کی علمی اور اخلاقی حالت پر دل گرفتہ بھی رہتے تھے۔ اور کیوں نہ ہوتے… تعلق اُس نسل سے تھا، اُس بزرگ نسل سے جس کی آنکھوں کے سامنے یہ ملک وجود میں آیا تھا۔ ہجرت کا خونچکاں تجربہ بھی ساتھ تھا کہ کس طرح آگ اور خون کی ندیاں عبور کرکے سرحد کے اُس پار سے آئے تھے، اور یہاں آئے تو سر پہ کھلا آسمان تھا اور پائوں جوتوں سے محروم تپتی زمین پہ دھرے تھے۔ کس کس طرح سے عمر کو کاٹا ہے میر نے کی جیتی جاگتی تصویر بھی تھے اور تفسیر بھی۔ کوئی ان کی تفصیل جاننا چاہے تو اے اے سید کا انٹرویو پڑھ لے جس میں ماضی کی دل گداز داستان موجود ہے… اُس بزرگ کی داستان جس کی نگاہوں کے سامنے خون میں نہایا ہوا یہ ملک دنیا کے نقشے پر ابھرا اور پھر گاہے گاہے خون میں نہاتا ہوا ایک بدنصیب کڑی ساعت میں دو ٹکڑے ہوگیا۔ کیا گزری ہوگی اُن دلوں پہ جن کا اس ملک کی تعمیر و تہذیب میں ذراسا بھی حصہ رہا ہوگا۔
تعلیم و تعلّم سے فارغ ہوکر انھوں نے درس و تدریس کا پیشہ اپنایا تو اسی لیے کہ کوئی قوم اگر واقعی قوم بنتی ہے تو علم ہی کی روشنی سے۔ تو خیال ہوا کہ زندگی کو اسی مقصد کے لیے کھپادو۔ استاد کی حیثیت میں بھی روایتی استاد نہیں رہے۔ صحیح معنوں میں استاد رہے۔ کئی مضامین کے نصاب تیار کیے جو آج بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ درسی کتابوں کی تدوین میں حصہ لیا۔ طالب علموں پر انفرادی توجہ دی۔ ملک میں نفاذِ اسلام کو ملک کی تقدیر جانا تو جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی، اور آخری سانس تک اس رشتے کو نبھایا، لیکن جماعت سے ہٹ کر اپنی شخصیت اور شناخت بنائی۔ دیکھنے میں تونہیں لیکن ملنے ملانے اور برتنے میں، رویّے میں کہیں سے بھی اس جماعت کے نہیں لگتے تھے۔ وہ اُن میں سے نہیں تھے جو جماعتی عصبیت میں مبتلا ہوکر اپنی ہی پارٹی کی بت پرستی میں مبتلا ہوجاتے ہیں کہ یہ رجحان تمام ہی پارٹیوں کے ورکروں اور حامیوں میں پایا جاتا ہے۔ اپنی جماعت پر جائز تنقید کو تسلیم کرلینے کا بھی ان میں حوصلہ تھا، اور یہ ان کی ذہنی اور قلبی کشادگی اور کشادہ نظری تھی۔ شادی بیاہ کی تقریب میں نکاح خوانی کا فریضہ بھی انجام دے دیتے تھے اور ایسی تقریبوں میں بڑی سنجیدہ تقریر کرتے تھے جس میں علم کی روشنی ہوتی تھی، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلی ہوئی ایسی نصیحتیں جو دل میں اترتی چلی جاتی تھیں۔ یہ ان کا ایک اور روپ تھا، اُس روپ سے بالکل مختلف جو مشاعروں میں ظاہر ہوتا تھا۔ ہر آدمی میں ہوتے ہی دوچار آدمی ہیں، اسی طرح ان میں بھی کئی آدمی تھے۔ ایک آدمی وہ جو ہنستا ہنساتا تھا، محفلوں میں جان ڈال دیتا تھا۔ ایک وہ جو اندر سے زخمی تھا، غمزدہ تھا اُن صعوبتوں کے ہاتھوں جو ان پر زندگی بھر ٹوٹتی رہیں۔ بیٹے کا انتقال، بیوی کی بیماری، گھریلو زندگی کی ناآسودگیاں اور جانے کیسی کیسی پریشانیاں… لیکن اسلوب و انداز زندگی کا ایسا رہا کہ کبھی زبان پر شکوہ نہ آیا، کبھی کسی سے حرفِ شکایت ادا نہ کیا۔ صبر و رضا کا قابلِ رشک نمونہ بنے رہے۔ اپنی صعوبتیں اور مصیبتیں اپنے لیے، اپنی ہی ذات کی حد تک۔ ان میں ایسی خودداری اور خدا شناسی تھی کہ کبھی اس میں کسی کو شریک کرنے کے روادار ہی نہ ہوئے۔ کہنے دیجیے کہ خوشیاں بانٹنے کے لیے دوسروں کے سامنے مسخرہ بننے سے بھی گریز نہ تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کی شخصیت کے اس روپ بہروپ کو کیا نام دیں۔ کیا اسے تضاد کہیں، ٹکرائو کہیں کہ شخصیت کے دریا کے یہ دو کنارے ایسے تھے جو آپس میں کہیں ملتے ملاتے ہی نہ تھے… مگر شخصیت کا دریا پھر دریا تھا، بہتا رہا، سیراب کرتا رہا، قرب و جوار کی کھیتیوں کو۔ سنجیدگی، قہقہہ، آنسو اور ہنسی کے تال میل سے بنی اس ہستی میں… ہاں ہستی میں جو متبرک ہوتی ہے، مقدس ہوتی ہے، وہ ایسے ہی متبرک و مقدس تھے۔ او ریہ بات لکھتے ہوئے میں پُراعتماد ہوں کہ کبھی اس پہ مجھے معذرت خواہ نہ ہونا پڑے گا۔ ان کے کلام پر بہت پہلے میں نے ایک تفصیلی مضمون قلمبند کیا تھا جو ایک رسالے کی، اور پھر ان کی کتاب کی زینت بنا۔ اس میں ان کا ایک شعر بطور حوالہ نقل کیا تھا۔ یہ شعر جب پڑھا تھا تو دل میں اتر گیا تھا۔ اس لیے کہ ایسے معاشرے میں رہتا تھا جہاں لالچ، حرص و ہوس، مادی آسائشوں کے حصول کی دوڑ لگی تھی۔ ہر طرف مقابلہ بازی، سامانِ تعیشات اکٹھا کرنے کا مقابلہ، دولت جمع کرنے اور اس دوڑ میں دوسروں سے آگے نکل جانے کی بے پناہ خواہش… اور واقعی ایک لامتناہی دوڑ کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے۔
جو مجھے دیا ہے مجھے اسی کا حساب دینے کی فکر ہے
مجھے اس سے کوئی غرض ہو کیا اسے کیا دیا اُسے کیا دیا
اس مادی دنیا میں مادی بھاگ دوڑ کی فضا میں یہ آواز، یہ پاکیزہ آواز دوڑتے بھاگتے آدمی کو ایک لمحے کے لیے روک دیتی ہے، چونکا دیتی ہے۔ اچھا تو یہ جمع تفریق کا حساب کتاب جو ہم یہاں کرتے رہتے ہیں، اسی کا کہیں اور بھی حساب دینا ہے، اور جب کہیں اور حساب دینا ہی ٹھیرا تو پھر یہ کیوں دیکھا جائے کہ کس کس کو کیا کیا ملا۔ مجھے تو یہی فکر ہونی چاہیے کہ مجھے جو ملا کہاں سے ملا، صحیح ملا یا غلط۔جائز ملا کہ ناجائز۔ حرام ملا کہ حلال۔
دیکھیے شعر میں کہیں بھی یہ بحث نہیں ہے۔ اس لیے کہ حرام و حلال کی بحث سن سن کر ہم ایسے عادی ہوگئے ہیں کہ یہ الفاظ اپنے معنی کھو بیٹھے ہیں۔ اب حرام اور حلال کے لفظ ہمارے اندر کوئی احساس بیدار نہیں کرتے۔ ہاں اسے کیا ملا اور اُسے کیا ملا کی تکرار ہمارے اندر سوچ کا نیا زاویہ پیدا کرتی ہے۔ اپنے احوال پر سوچنے کی ایک لہر اٹھتی ہے اور پھر ڈوب جاتی ہے۔ اس لیے کہ شاعر احساس اور جذبے کو آواز دیتا ہے، لیکن جس نظام کی بنیاد ہی مال و منال کی محبت اور ہوس پر ہو، اس نظام کو ڈھائے بغیر نہ معاشرے کو پاکیزہ بنایا جا سکتا ہے اور نہ آدمی کو سیدھے سبھائو راہ پر لایا جا سکتا ہے۔
عنایت علی خاں جو پروفیسر بھی تھے، انھوں نے اے اے سید کے انٹرویو میں کہا تھا کہ شاعری سے زیادہ مجھے اپنے استاد ہونے کی حیثیت پر فخر ہے۔ بلاشبہ معلمی افضل ہے شاعری پر۔ علم سے انسان کی شناخت ہے، علم سے ہی انسان افضل ہے، اور علم میں ہی انسان کی نجات ہے۔ شاعری جذبات کی تہذیب کرتی ہے، لیکن علم اور آدمی صاحبِ علم نہ ہو تو شاعری کی افادیت سے بھی بے خبر ہی رہتا ہے۔ اسے علم ہی بتاتا اور سکھاتا ہے کہ شاعری سے اپنے جذبات کو مہذب بنائو۔ اس لیے پہلے علم ہے اور پھر شعر و ادب۔ تو آدمی کی جو فضیلتیں ہیں، پروفیسر عنایت علی خان ان فضیلتوں سے بہرہ ور تھے۔ اب وہ دنیا میں نہیں ہیں مگر ان کے مجموعہ ہائے کلام موجود ہیں۔ ان کے بنائے ہوئے نصابوں سے آج بھی طلبہ فیض یاب ہورہے ہیں۔ ان کے شاگردوں کا ایک سیلاب ہے جو ان کی عمر بھر کا حاصل ہے، ساری زندگی کی کمائی ہے۔ چاہے وہ پروفیسر صاحب کی امیدوں پر پورے نہ اترے ہوں لیکن ان میں نیکی اور خیر کا ذرا سا عنصر بھی جگمگاتا ہے تو اسے پروفیسر عنایت علی خاں ہی کا فیض جاننا چاہیے۔