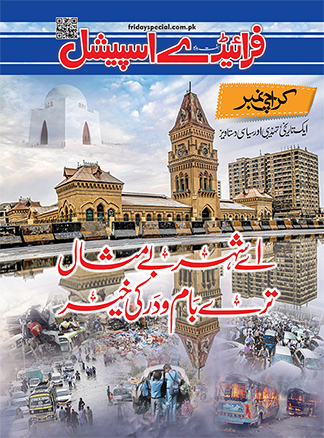عبدالکریم عابد صاحب کو میں نے صرف ایک بار دیکھا تھا۔ یہ زمانہ میری طالب علمی کا تھا۔ میں کالج میں ایف اے میں تھا اور غالباً اپنا کوئی مضمون دینے ’’جسارت‘‘ کے دفتر گیا تھا۔ ایڈیٹر عبدالکریم عابد ہی تھے۔ جب میں ان کے کمرے کے پاس پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا۔ دفتر میں سناٹا تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک صاحب سیاہ رنگت مائل، کسی قدر دراز قامت، پینٹ شرٹ پہنے ٹہل رہے تھے۔ کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ اب یہ بتانا مشکل ہے میرے لیے کہ انہیں میں نے کیسے پہچانا۔ ممکن ہے کسی سے پوچھا ہو، یا ان کی کوئی تصویر دیکھ رکھی ہو۔ لیکن تصویر دیکھنے کا امکان معدوم تھا کہ اُس زمانے میں مضمون نگاروں کے مضامین کے ساتھ ان کی تصویریں چھپنے کا رواج نہیں تھا جیسا کہ آج کل ہے۔ بہرحال میں ان کے نام اور کام دونوں سے واقف تھا۔ وہ زمانہ نظریاتی خلیج کا تھا۔ بھٹو صاحب کے سیاسی عروج کے ساتھ ہی سارا ملک اور یہاں کے لکھنے پڑھنے والے واضح طور پر دائیں اور بائیں بازوئوں میں منقسم ہوگئے تھے۔ ایشیا کو بھی سبز اور سرخ میں رنگ دینے کا جھگڑا پڑا ہوا تھا۔ بائیں بازو والے ملک کو ماسکو اور پیکنگ بنادینے کے آرزومند تھے، تو دائیں بازو والے اسے مکہ و مدینہ میں بدل دینے کا خواب دیکھتے تھے۔ بھٹو صاحب کا فلسفہ اسلامی سوشلزم صحافتی میدان میں بحث و نزاع کا موضوع بنا ہوا تھا۔ اس کا کوئی اور فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن ان علمی مباحث سے ہماری صحافت کی فکری سطح بلند ہوگئی تھی۔ مارکس، لینن اور مائو کے نظریات کا پوسٹ مارٹم ادارتی صفحوں پر ہوتا تھا، تو بائیں بازو کے لکھنے والے جماعت کا رشتہ امریکہ سے جوڑنے کے لیے دور کی کوڑی لاتے تھے۔ اس پس منظر میں اُن دنوں جن لکھنے والوں کی تحریریں سنجیدہ، تجزیاتی اور فکر انگیز ہوتی تھیں، ان میں عبدالکریم عابد کا نام سب سے نمایاں تھا۔ اُس زمانے کی جذباتی اور کسی قدر اشتعال انگیز فضا میں عابد صاحب کی تحریروں کا لب و لہجہ نہایت متین اور شائستہ ہوتا تھا۔ وہ پڑھنے والوں کے جذبات سے کھیلنا نہ جانتے تھے۔ اپنی بات کو دلیل سے مضبوط بناتے تھے۔ واقعات کا تجزیہ کرکے ان سے نتائج اخذ کرتے تھے۔ اسلوبِ تحریر میں رنگینی کے بجائے گہری سنجیدگی ہوتی تھی، لیکن ایسی سنجیدگی نہیں جس میں یبوست ہو، خشکی اور بے رنگی ہو۔ بلکہ تحریر میں ایسی جاذبیت جو پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے کسی اور جانب متوجہ نہ ہونے دے۔ چناں چہ عابد صاحب نے ان دنوں لکھا اور خوب لکھا۔ جن مباحث سے اخبارات کے صفحات گرم تھے اور ان سے دھواں سا اٹھتا تھا، گاڑھا گاڑھا سا سیاہ دھواں… جس سے ملکی سیاست اور صحافت کی فضا میں بادل سے اڑتے پھرتے تھے۔ یہ سوچنے سمجھنے والوں کے اندر کا دھواں تھا، گھٹن تھی یا فکر کی چبھن تھی کہ جس نے شہری آبادی کی تعلیم گاہوں، کیفوں اور چائے خانوں اور جلسے جلوسوں کو بے آرام کررکھا تھا۔ عابد صاحب جیسے لکھنے والے جو کچھ لکھتے تھے، اپنے حلقۂ فکر کو سوچنے کی جو غذا فراہم کردیتے تھے، وہ ان ہی دلیلوں اور ان ہی تجزیوں کو بحث و مباحثے میں اگلتے رہتے تھے۔ بعض لکھنے والے فقرے بازی کرتے تھے، بعض نعرے بازی، اور بعض دلیل بازی۔ لیکن عابد صاحب تجزیہ کرتے تھے۔ ان کے تجزیوں کا خاص پہلو واضح اور صاف اندازِ فکر جس میں کوئی الجھائو، کوئی پیچیدگی، کوئی ابہام نہ ہوتا تھا۔ وہ پڑھنے والوں کو سیدھا رستہ دکھاتے تھے۔ سیدھا رستہ جو شاید سب سے پیچیدہ رستہ ہوتا ہے۔ اسی پہ چلتے ہوئے آدمی الجھتا اور بھٹکتا ہے۔ لیکن عابد صاحب نہ الجھاتے تھے اور نہ بھٹکاتے تھے۔ وہ قاری کو موضوع پر اپنی منزل تک پہنچا دیتے تھے… اطمینان بخش منزل پر کہ پڑھنے والا کہتا یا محسوس کرتا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے اور یہ بات ایسی ہی ہے۔ میری عقل اسے تسلیم کرتی ہے۔ حق یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔
تو اس دوپہر کو جب میں نے عابد صاحب کو ٹہلتے ہوئے اپنے کسی خیال میں گم دیکھا تو ہمت نہ پڑی کہ انھیں مخاطب کر کے ڈسٹرب کروں۔ اپنے جس خیال میں گم ہیں، وہاں سے انھیں کھینچ نکالنے کی گستاخی کروں۔ ویسے بھی مجھے ایسے لوگ ہمیشہ اچھے لگتے ہیں جو کچھ سوچ رہے ہوں۔ سوچنا بھی ایک کام ہے۔ دنیا کا سب سے قیمتی اور انمول کام۔ اسی لیے مجھے سلیم احمد ہمیشہ اچھے لگے، اور اسی لیے اس روز عابد صاحب بھلے لگے کہ وہ سلیم احمد کی طرح کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ملے۔ تو میں عابد صاحب سے نہ ملا۔ کچھ ایسا یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد ایک آدھ بار ان کے دفتر میں ان سے ملنے کا شرف حاصل ہوا، اور میں نے انھیں کم گو، کم سخن پایا۔ اپنے مضامین کی طرح سنجیدہ سنجیدہ سے… لیکن سنجیدگی کے ساتھ شائستگی اور شستگی بھی تھی۔ پھر جب ان کی وفات کے بعد ان کی خودنوشت ’’نصف صدی کا قصہ‘‘ پڑھی تو کھلا کہ انھوں نے کیسی بھرپور زندگی گزاری ہے۔ یہ خودنوشت مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اگلے حصے کی اشاعت کا وعدہ بھی کیا گیا تھا۔ نہیں معلوم وعدے کی تکمیل ہوئی یا نہیں۔ ان کے ہونہار اور لائق فرزند سلمان عابد ورثے میں جنھیں والد مرحوم سے صحافت کا پیشہ اور لکھنے پڑھنے کا ہوکا میسر آیا ہے، عابد صاحب پر انھوں نے معاصرین کی تحریروں کا ایک گلدستہ مرتب کیا: ’’عبدالکریم عابد، ایک شخص ایک عہد‘‘۔ اسے بھی پڑھ کر پتا چلتا ہے کہ عابد صاحب نے اپنی فکر سے اپنے زمانے کے اذہان کو کس طرح متاثر کیا… اور یہ بھی کہ وہ کتنے شریف النفس، کتنے بے غرض اور صاحبِ احوال انسان تھے۔ اخباری دنیا بالعموم سازشوں اور توڑ جوڑ کا گڑھ ہوتی ہے۔ معاشرے پر احتساب کا شکنجہ کسنے والے اداروں میں ترقی کرنے، آگے بڑھنے اور دنیا کمانے کے لیے جو کچھ ہوتا اور جو کچھ کیا جاتا ہے، اس کی تصویر اگر دنیا کو دکھا دی جائے تو معاشرہ ان ذرائع ابلاغ کے اداروں سے محاسبے کا حق واپس لینے پر مُصر ہوجائے۔ لیکن عابد صاحب ان معدودے چند صحافیوں اور مضمون نگاروں میں تھے جنہوں نے کسی عہدے سے چمٹے رہنے کے لیے کبھی کوئی اوچھا ہتھکنڈہ اختیار نہیں کیا۔ یہاں تک کہ انھوں نے اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کے توڑ کی بھی فکر نہیں کی۔ انھیں اپنے قلم پر اور اپنے خیالات پر اعتماد تھا۔ ساری زندگی انھوں نے ان ہی پہ بھروسا کیا۔ اسی کی روٹی توڑی۔ وہ بھلے مانس تھے اور بھلے مانس ہی کی طرح جیا کیے۔ مسلسل و متواتر لکھتے رہے، اس سے بھی بے نیاز ہو کے کہ ان کے لکھے کا کوئی اثر ہوتا بھی ہے یا نہیں… اور لکھ لکھ کر اپنے قد میں اضافہ کرنا اور پھر اس کی قیمت وصول کرنا جو اُن دنوں بھی بہت سے لکھنے والوں کا وتیرہ تھا اور آج تو سکہ رائج الوقت ہے… عابد صاحب ان چلّتر بازیوں سے ناواقف تھے۔ ان کا مزاج ان چیزوں سے لگّا کھاتا ہی نہ تھا۔ چناں چہ میرے ذہن میں ان کا امیج ہمیشہ ایک محترم صحافی، ایک معزز لکھاری کا ہی رہا۔
باقی رہی بات کہ کیا ان کے پیشے نے انھیں وہ کچھ دیا جس کے وہ واقعی مستحق تھے۔ مجھے یہ سوال اٹھانے کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے کہ جس مقام کی طلب و جستجو سے بے نیاز ہوکے عابد صاحب نے قلم کا فرض اور قرض ادا کیا اس کے لیے مجھے یا کسی اور کو فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں۔ کہیں اور بھی تو دنیا کی زندگی کا حساب کتاب ہونا ہے، تو عابد صاحب کا معاملہ وہیں کے لیے چھوڑ دینا بہتر ہوگا۔ انھوں نے شاید اسی لیے یہاں کی زیادہ فکر نہیں کی۔ وہاں کے عوض پر زیادہ یقین جو تھا!