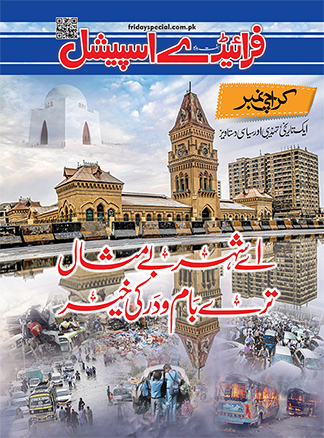اب کیا معلوم تھا ہمیں کہ اتنی جلدی انعام باری صاحب کی عمر کی نقدی ختم ہوجائے گی اور ہمیں ان کا تعزیت نامہ لکھنے کی اذیت سے گزرنا پڑے گا۔ جب تک بیماری دُکھی کے ساتھ جیتے تھے یہی یقین تھا کہ ابھی بہت دن اور جئیں گے، کیا خبر تھی اب مزید جینا، مزید تکلیفوں کے ساتھ زندگی کو بھگتنا قدرت کو منظور نہ ہوگا اور ایک رات، اسی رات جس دن، جمعہ کے دن میں ان کی عیادت کو لیاقت نیشنل اسپتال کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ گیا تھا، وہ دنیا سے رخصت ہوجائیں گے۔ صبح نیند سے جاگا تو موبائل پہ ان کے سعادت مند بیٹے عمر کا ایک سطری پیغام دیکھا: ’’ابا کا انتقال ہوگیا‘‘۔ اگر یک سطری پیغام یہ ہوتا کہ ’’میں یتیم ہوگیا‘‘ تو صدمہ اور جانکاہ ہوجاتا۔ ہر آنے والے کو دنیا سے جانا تو ضرور ہے کہ ہر ایک کا یہی مقدر ہے۔ لیکن جانے والا اپنے پیچھے کیا کچھ چھوڑ جاتا ہے، آدمی جب اس حقیقت پر غور کرتا ہے تو موت کا سانحہ ناقابلِ برداشت سا ہوجاتا ہے۔
انعام باری مرحوم سے ملاقات، شناسائی یا تعارف جو کہہ لیں، یوں تو زمانۂ طالب علمی ہی سے تھا کہ ہم ایک ہی شعبے کے فارغ التحصیل تھے۔ لیکن یہ شناسائی تب گہری دوستی میں بدل گئی جب انھوں نے ریڈیو پاکستان سے ریٹائرمنٹ لے کر شعبۂ ابلاغِ عامہ میں درس و تدریس سے اپنا تعلق استوار کیا۔ ان سے قریب ہوکر میں نے انھیں اچھی طرح جانا، اچھی طرح پہچانا، ان کی زندگی کے بہت سے ایسے رُخ سامنے آئے جو اس قربت کے بغیر جو ہم دونوں کو حاصل تھی، ان کی شخصیت اور مزاج کے ان رخوں سے واقفیت ممکن ہی نہ تھی۔ بے شک وہ سیلف میڈ آدمی تھے۔ انھوں نے اپنا کیریئر، اپنا مستقبل نہایت محنت و مشقت سے بنایا تھا۔ اوائل عمری ہی سے انھیں معاش کی چکی میں خود کو پیسنا پڑا۔ چناں چہ اس تلخ تجربے کو وہ عجب دل گداز طریقے سے بیان کرتے تھے۔ کہتے تھے: ’’ہم پہ جوانی کب آئی اور کب گزر گئی، پتا ہی نہ چل سکا‘‘۔ اس فقرے میں ان کے دل کا درد پوشیدہ تھا۔ آدمی کی حرماں نصیبی چھپی تھی۔ اس جملے میں اس معاشی اور معاشرتی نظام پہ تبصرہ تھا جو آدمی کو زندگی کی راحتوں اور مسرتوں سے محروم کردیتا ہے۔ لیکن انھیں اپنے حالات سے کوئی لمبا چوڑا گلہ نہ تھا۔ بس ایک حسرت اندر تھی جو اس فقرے سے اپنا اظہار کردیتی تھی۔ باقی وہ ایک زندہ دل اور زندگی سے بھرپور انسان تھے۔ وہ اُن اساتذہ میں تھے جن سے طلبہ و طالبات اس لیے متاثر ہوتے تھے کہ ان کی کلاس میں بیٹھ کر علم میں اضافہ ہوتا تھا۔ جو کچھ وہ نہیں جانتے تھے وہ جان لیتے تھے۔ وہ طلبہ کو کلاس کے بعد بھی وقت دیتے تھے۔ انھیں اپنے نصابی موضوعات پر کتابیں پڑھنے کا مشورہ ہی نہیں دیتے تھے، اپنی ذاتی کتابیں بھی دے دیا کرتے تھے۔ ان میں ڈسپلن کی سختی کے ساتھ طالب علموں کے لیے شفقت بھی بے انتہا تھی۔ اسی لیے وہ طلبہ میں ہردلعزیز تھے۔ ہمارے احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں: ’’اچھا استاد وہ ہے جو طالب علموں کا محبوب بن جائے‘‘۔ اس اعتبار سے وہ پڑھنے لکھنے کے شوقین طلبہ میں یقیناً محبوب نظر آتے تھے۔ ہماری ان کی دوستی میں ایک مشترک قدر یہ تھی کہ ہم دونوں ہی شائقِ مطالعہ تھے۔ ہمارے درمیان کتابوں کے لین دین کا بھی تعلق تھا۔ وہ کتابیں دے کر بھی، اور لے کر بھی… دونوں صورتوں میں بھول جاتے تھے۔ اور اپنا حال اس کے بالکل برعکس تھا اور ہے۔ اگر کسی نے پچیس تیس سال پہلے بھی خاکسار سے کتاب لی اور واپس نہیں کی تو بھولنے کا کوئی سوال نہیں۔ اب یوں سمجھیے کہ اس معاملے میں حافظہ اونٹ کا پایا ہے۔ یہ الگ بات کہ کتاب کا تقاضا کرنا طبیعت کو کبھی گوارا نہ ہوا۔ کتاب ہی کے ناتے سے ایک اور قدرِ مشترک یہ تھی کہ جو کتب فروش لائبریری کے لیے مہنگی انگریزی کتابیں فروخت کے لیے لاتے تھے، ہم دونوں ہی بہ حالتِ مجبوری لائبریری کے لیے منظور تو کرلیتے، لیکن ساتھ ہی اپنے مطلب کی کتابیں فوٹو اسٹیٹ بھی کرا لیتے تھے۔ ایسی عکسی کتابوں کا ڈھیر ان کے پاس بھی جمع ہوچکا تھا اور میرے پاس بھی ہے۔
اُن دنوں جب میں لیکچرار ہوا تو باری صاحب کوآپریٹو ٹیچر کے طور پر پڑھانے آتے تھے۔ ضمنی مضامین میں چوں کہ طلبہ کی تعداد زیادہ ہوتی تھی تو انھیں ایک سے زاید گروپوں میں تقسیم کردیا جاتا تھا۔ ایک گروپ باری صاحب اور دوسرا اس خاکسار کے پاس ہوتا تھا۔ کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی ہم دونوں بیٹھ جاتے تھے اور اپنے اپنے نوٹس ایکسچینج کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ وہ مجھے بتاتے تھے کہ آج وہ کیا پڑھائیں گے، اور پھر میں اُن سے عرض کرتا تھا کہ آج کے لیکچر کی میں کیا تیاری کرکے آیا ہوں۔ اس طرح ہم دونوں کو ایک دوسرے سے فائدہ پہنچ جاتا تھا۔ ان سے قربت میں اور گہرائی آگئی جب وہ شعبے کے مستقل استاد ہوگئے اور پھر کیمپس ہی میں رہائش ہوگئی۔ ہمارے گھروں کے درمیان بھی کوئی زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ ہم ایک ہی مسجد میں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک عرصے تک تو فجر کی نماز کے بعد ہم ہوا خوری کی نیت سے چہل قدمی کرتے دور نکل جاتے تھے۔ ہماری جوانی تھی اور ان کی ادھیڑ عمری۔ بحث و مباحثہ ہم دونوں کے درمیان دھواں دھار طریقے سے ہوتا تھا۔ ہار ماننے کو وہ بھی تیار نہ ہوتے، پیچھے ہٹنے میں مجھے بھی تامل ہوتا۔ جب جوانی ڈھلنے لگی اور جوشِ جذبات سرد پڑنے لگے تو میں نے ان کی عمر کے لحاظ میں ہتھیار پھینک دیے۔ وہ جو کہتے اس پر آمنا صدقنا کہنے لگا۔ انھوں نے اپنی عمر کا بڑا حصہ ریڈیو پاکستان کے شعبۂ خبر میں گزارا تھا۔ وہاں کی بری بھلی یادیں ذہن میں محفوظ تھیں جنہیں دہرا کر وہ ہمیں محظوظ کرتے تھے۔ انھیں موسیقی سے بھی خاص لگائو تھا۔ ان کی اپنی آواز میں بھی رس تھا۔ دوسروں کی زبانی سنا تھا کہ اچھا گاتے ہیں لیکن ہمیں کبھی اس لائق نہ سمجھا کہ کچھ سنائیں۔ نہ ہم نے کبھی ان سے فرمائش کی۔ اس کی بڑی وجہ ان کا احترام تھا۔ سیاسی یا علمی موضوعات پر بحثا بحثی ایک الگ معاملہ تھا، لیکن جہاں تک ان کے احترام اور بزرگی کا خیال تھا، اس میں کبھی کمی نہیں کی۔ خوش خوراک تھے۔ اچھے کھانے ان کی کمزوری تھے۔ بیماری کے دنوں میں بھی کوئی دوست آجاتا تو اس کو ساتھ لے کر جاکر جاوید کی نہاری کھانا کبھی نہ بھولتے۔ مزاج میں شدت تھی۔ جو رائے ایک بار قائم کرلیتے، خواہ کسی کی شخصیت کے بارے میں سہی، اس سے بہت مشکل سے رجوع کرتے۔ لیکن دوستوں کے دوست تھے۔ جب یہ خاکسار شعبے کا چیئرمین ہوا تو ان کی صلاحیتوں سے شعبے کے لیے بہت کام لیے گئے۔ ایک نیوز لیٹر بہ زبان انگریزی ’’میڈیا مرر‘‘ نکالا۔ اس کی تمام خبریں باری صاحب ہی بناتے تھے۔ انگریزی ان کی غیر معمولی طور پر اچھی تھی۔ اس کا اداریہ میں اردو میں لکھ دیتا تھا، وہ اس کا بامحاورہ ترجمہ کر ڈالتے تھے۔ اس نیوز لیٹر میں انگریزی اخبارات میں میڈیا سے متعلق چھپنے والی خبریں یکجا کردی جاتی تھیں اور باقی شعبے کی سرگرمیوں کی اطلاعات ہوتی تھیں۔ یہ بہت عمدہ تجربہ تھا۔ مرحوم ضمیر نیازی اور پروفیسر شریف المجاہد صاحبان نے اس نیوز لیٹر کی تعریف و توصیف میں خطوط لکھے جو شائع بھی ہوئے۔ ان ہی دنوں مجھے شدت سے احساس ہوا کہ باری صاحب نے ابھی تک پی ایچ ڈی نہیں کی ہے جو آگے چل کر ان کے ٹیچنگ کیریئر میں رکاوٹ کا سبب بنے گا۔ میں نے انھیں اس پر اُکسایا۔ وہ پی ایچ ڈی میں رجسٹریشن کے لیے تیار بھی ہوگئے۔ موضوع بھی تبادلہ خیال کے بعد طے پا گیا۔ لیکن ان کی ذات کے ساتھ ان کے اپنے پیدا کردہ بکھیڑے ایسے تھے جو انھیں جم کر کوئی علمی اور تحقیقی کام کرنے ہی نہ دیتے تھے۔ کبھی بیٹھے وائس چانسلر صاحب کی تقریر لکھ رہے ہیں، کبھی کسی مجلس میں خود تقریر کے لیے چلے جارہے ہیں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ میں انھیں سمجھاتا، کبھی ناراض بھی ہوتا، مثالیں بھی دیتا کہ فلاں نے اپنی نالائقی کے باوجود پی ایچ ڈی کرلی، آپ میں کیا کمی ہے۔ زبان پر عبور ہے، علم وافر مقدار میں ہے، کتابیں سب موجود ہیں، آپ کو صرف وقت نکال کر اور ٹانگیں توڑ کر میز کرسی پر بیٹھنا ہے، آسانی سے سال دو سال میں مقالہ تیار ہوجائے گا۔ وہ اچھا زمانہ تھا، آج کل کی طرح کورس ورک وغیرہ کا ٹنٹا نہ تھا۔ یک سو ہوجاتے اور دل جمعی سے لگ جاتے تو پی ایچ ڈی کرنا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اب اور کیا کہا جائے کہ نصیب میں لکھا ہی نہ تھا کہ نام کے ساتھ ڈاکٹر لگے، اور دس ہزار روپوں کی تنخواہ میں پی ایچ ڈی الائونس کا اضافہ ہو۔ ہماری چیئرمینی کے زمانے ہی میں ڈیپارٹمنٹ کی نئی بلڈنگ تعمیر ہوئی۔ اس کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے تین ساڑھے تین کروڑ کی گرانٹ لی گئی۔ اس کے سارے کاغذات کی خانہ پُری باری صاحب ہی نے کی۔ پھر اس بلڈنگ میں ایف ایم ریڈیو سے اسی زمانے میں نشریات شروع ہوئیں۔ یہ بھی میری درخواست پر ان ہی کی نگرانی میں ہوا۔ اُن کے ان سارے کارہائے نمایاں پر غور کرنے سے اس نتیجے پر پہنچا کہ باری صاحب میں Initiative کی بہت کمی ہے۔ یعنی کسی بھی کام میں پہل کرنے کا خیال یا ہمت کا ان میں بہت فقدان ہے۔ البتہ خارج سے ان پر وہ کام ایک ذمہ داری کے طور پر تھوپ دیا جائے تو وہ نہایت فرض شناسی سے اسے ادا کرنے پر تیار ہوجاتے ہیں، بلکہ اسے ادا کر بھی دیتے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی سے ریٹائر ہوکر وہ ضیاء الدین یونیورسٹی میں کھلنے والے میڈیا کے شعبے سے وابستہ ہوگئے۔ اس طرح ان سے رابطہ تقریباً منقطع سا ہوگیا۔ جب میں شعبے کی نئی بلڈنگ میں دوبارہ چیئرمین ہوا تو وائس چانسلر صاحب کی خصوصی اجازت سے انھیں ایف ایم ریڈیو کے نگراں کی حیثیت سے شعبے میں واپس لے آیا۔ وہ اپنے شعبے میں لوٹ کر بہت خوش تھے۔
ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی انھیں ایک عجیب قسم کے درد کی بیماری نے آ گھیرا۔ درد ایسا تھا کہ چلنے پھرنے سے معذور ہوجاتے تھے۔ جس نے بھی ہمدردی میں کسی ڈاکٹر کا پتا بتایا، یہ اُس ڈاکٹر کے پاس ضرور پہنچے۔ درد گھٹتا بڑھتا تھا لیکن کامل افاقہ کبھی نہ ہوا۔ شاید ان ہی اُلٹی سیدھی دوائوں کے استعمال سے ان کے دونوں گردے ناکارہ ہوگئے اور انھیں ڈائیلائسس کرانے پر مجبور ہونا پڑا۔ ہفتے میں تین دن اس تکلیف دہ عمل سے انھیں گزرنا پڑتا۔ ان کے سعادت مند بیٹے عمر نے جس محنت اور وفاشعاری و اطاعت گزاری سے باپ کی خدمت کی، جس نے دیکھا وہ اش اش کر اُٹھا۔ شکر خدا کا، باری صاحب نے کسی نہ کسی طرح کراچی یونیورسٹی ایمپلائز سوسائٹی میں اپنا گھر بنالیا تھا۔ بیماری سے قبل وہ جناح وومنز یونیورسٹی میں ڈین کے عہدے پر فائز رہے۔ طبیعت کی ناسازی نے انھیں مزید کام کے قابل نہ چھوڑا۔ اسپتال میں داخل ہونے سے چند روز قبل وہ امریکہ سے آئے دوست جمال محسن کے اعزاز میں طارق محمود میاں کی طرف سے دی گئی ہائی ٹی کی دعوت میں شریک ہوئے۔ وہ وہیل چیئر پر بیٹھ کر نقل و حرکت کررہے تھے۔ ان کے بیٹے عمر کو یہ کہہ کر کہ بھئی تم تو یہ ذمہ داری ادا کرتے ہی ہو، آج یہ خدمت ہمارے سپرد کرو، میں نے ان کی وہیل چیئر کو آگے دھکیلنا شروع کیا۔ باری صاحب نے مڑ کر دیکھا، مسکرائے۔ مسکراہٹ میں چھپی نقاہت نمایاں ہوگئی۔ تب کہاں معلوم تھا کہ تعلق کا یہ دھاگا اگلے دو ایک ہفتے ہی میں ٹوٹ جائے گا اور باری صاحب سے پھر ملنا نہ ہوسکے گا۔ ہاں یہی زندگی ہے، مختصر سی، چند سانسوں کی، جس کے لیے ہم دنیا پر ریجھے جاتے ہیں، مرے جاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ… مگر جانے دیجیے، اگر نہ ہو یہ فریبِ پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ خداوند تعالیٰ ان کی روح کو شاد کام رکھے۔ بہت دین دار آدمی تھے۔ جملہ فرائضِ دینی کا اہتمام کرتے تھے۔ ان سے تعلق بہت گہرا تھا۔ جب تک سانس باقی ہے، یاد آتے رہیں گے۔