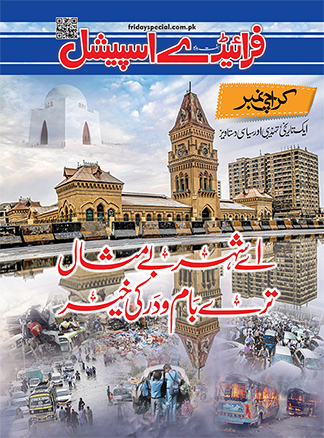ایک دن میرے عزیز سینئر دوست اور شاعر خوش نوا شوکت عابد نے پوچھا: ’’کیا تمہاری حال فی الحال میں عطاء اللہ حسینی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے؟‘‘
یہ سننا تھا کہ دل پر ایک گھونسا سا پڑا۔ برسوں پہلے غالباً 1997ء میںوہ اچانک یاد آئے تھے اور میں بے اختیار ان سے ملنے چلا گیا تھا۔ واپسی پر اس ملاقات کے تاثرات ’’بھولے بسرے کالج میں ایک شام‘‘ کے عنوان سے رقم بھی کیا تھا، جو پہلے کالم کے طور پر چھپا اور پھر میرے کالموں کی کتاب ’’دل سوز سے خالی ہے‘‘ میں شامل ہوا۔ کالم کے اختتام پر اپنے استاد محترم سے کیا ہوا یہ وعدہ بھی درج تھا کہ سر! میں آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ جس پر استاد محترم نے سراٹھا کر اس طرح دیکھا جیسے وعدے کا اعتبار نہ آیا ہو۔ یہ آخری فقرہ تب بے اختیار ذہن میں در آیا جب شوکت نے پوچھا کہ عطاء اللہ حسینی صاحب سے حال فی الحال میں ملاقات ہوئی ہے؟ ملاقات تو تبھی ہوتی جب ان سے ملنے جاتا۔ میں وعدہ کر کے آیا اوربھول گیا۔ آج کل کی زندگی اتنی ظالم اور بے رحم ہے کہ وعدوں کو بھلانے میں دیر نہیں لگاتی۔ وعدہ،کسی سے صدق دل سے کیا ہوا وعدہ ناگاہ یاد بھی آجائے تو کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آجاتی ہے اور ہم سر جھٹک کر کسی فوری کام میں خودکو گم کردیتے ہیں اور بے چارہ وعدہ بے بسی سے منہ تکتا رہ جاتا ہے۔ میں نے شرمندگی سے جواب دیا: ’’جانا تھا، کئی بار ارادہ بھی کیا، لیکن نہ جا سکتا‘‘۔ ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹھکا اور پھر اپنے احساس ندامتپر قابو پا کر پوچھا: ’’آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟‘‘
’’حسینی صاحب اب ویسے نہیں رہے جیسا تم نے انہیں دیکھا تھا۔ وہ بالکل بدل گئے ہیں‘‘۔ شوکت نے کہا اورمیں حیران ہوا۔
’’اچھا‘‘ میں نے اچھا کو ذرا کھینچ کر کہا۔
’’مگر وہکیسے؟‘‘
یہ تو مجھے نہیں۔لیکن حقیقت یہی ہے کہ حسینی صاحب اب وہ حسینی صاحب نہیں رہے‘‘۔ شوکت نے اطمینان سے کہا اور میرے اندر ایک تجسس سا جاگ پڑا۔
’’کیا چلیں‘‘ مل کر آئیں‘‘۔ میں نے مضطرب ہو کر کہا۔
’’چلو چلتے ہیں‘‘۔ شوکت نے آمادگی ظاہر کی۔ اور یوں ہم دونوں جامعہ ملیہ ملیر کی طرف روانہ ہوئے۔ حسینی صاحب نے اپنی ساری زندگی اسی کالج کی نذر کر دی۔ ڈاکٹر محمود حسین وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی نے اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر ذاکر حسین یک از بانی جامعہ ملیہ دہلی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ کالج قائم کیا تھا جس کے احاطے میں پرائمری وسیکنڈری اسکول، ٹیچرز ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ وغیرہ بھی تھے اور ساتھ ہی طلبہ کے لیے اقامت گاہیں (ہاسٹلر) بھی جن میں دوسرے شہروں اور دور دراز کے علاقوں کے طلبہ مقیم تھے۔
حسینی صاحب ان اساتذہ میں تھے جو اپنے طلبہ کو صرف اپنا شاگرد نہیں سمجھتے تھے، اپنی اولاد سے بڑھ کر انہیں عزیز رکھتے تھے۔ کلاس روم سے نکل کر بھی اپنے شاگردوں سے رابطے میں رہتے تھے۔ میں بھی ان طالب علموں میں شامل تھا جن پر ان کی نظر عنایت تھی۔ کالج کے اوقات کے بعد میں ان کی قیام گاہ پر چلا جاتا تھا جو کالج کے احاطے ہی میں تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے گفت و شنید کے بعد ماحضر تناول کروائے بغیر جانے دیا ہو۔ ان کا ڈرائنگ جو انکی مطالعہ گاہ بھی تھا، جن شیلفوں پر مختلف موضوعات پر کتابیں سلیقے و ترتیب سے رکھی رہتی تھیں۔ جب وہ بول رہے ہوتے تھے تو میرے کان انکی آواز پر اور نگاہیں کتابوں کے طواف میں مصروف رہتی تھیں۔ان ہی دنوں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کا بوجھ آج تک دل میں محسوس کرتا ہوں اور اس کی تلافی کی کی کوئی اور صورت نہیں پاتا کہ اس کا ذکرکر کے اپنے ضمیر کو اس بوجھ سے آزاد کر دوں۔ میرے ذاتی حالات ان دنوں کچھ ایسے تھے کہ ہمارا خاندان مشرقی پاکستان کے ناگفتہ بہ صورت حال سے مجبور ہرکر کراچی ہجرت کر آیا تھا۔ ہم سعود آباد، ملیر میں اپنے چھوٹے چچا کے مکان پر مقیم تھے، یہ مکان دو ڈھائی کمروں پر مشتمل تھا جس میں دادا جان اور دادی جان کے علاوہ تین خاندان رہائش پذیر تھے۔ گھر میں اتنی گنجائش بھی نہ تھی کہ کسی مہمان کو اگر وہ اچانک آجائے تو اسے کہیں بٹھا کر اس کی تواضع کی جا سکے۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہواکہ دروازے پر دستک ہوئی، اتفاق سے میںگھر پہ موجود تھا، دریچے سے باہر جھانک کے دیکھا تو استاد محترم عطاء اللہ حسینی کی موٹر سائیکل کھڑی نظر آئی، میرے تو دونوں ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ دونوں کمروں میں خواتین موجود تھیں، کچھ بچے بھی تھے جو دیر سے اٹھنے کے عادی تھے اور وہ سو رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہ آسکا کہ استاد محترم کو اندر بلائوں توکہاں کس جگہ بٹھائوں اور تواضع کمروںمیں تو کیا اور کس سے چیز سے کروں کہ گھر میں مہمان داری و مہمان نوازی کے لیے کچھ ہوتا ہی نہ تھا۔ خود ہماری گزر اوقات جیسے کیسے ہو رہی تھی۔ بھٹو حکومت نے مشرقی پاکستان سے آئے ہوئے طلبہ کی فیس معاف کررکھی تھی ورنہ کالج میں پڑھنا پڑھانا بھی ممکن نہ ہوتا۔ تو جب استاد محترم نے دوبارہ دستک دی تو میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، بہن سے کہا اگر میرا پوچھیں تو کہہ دینا نہیں ہے۔ بہن نے دروازہ کھولا اور ایک پٹ ہٹا کر وہی جواب دے دیا جو میں نے اسے سکھایا تھا۔ استادمحترم تو چلے گئے لیکن تبھی سے میں اپنے ضمیر کے آگے مجرم ہو گیا۔کئی بار سوچا، ارادہ بھی کیا کہ جا کر سر کے پائوں پڑ جائوں اور اپنے اس جرم کا، بداخلاقی کا، جھوٹ کا، بدتہذیبی کا چاہے جو نام دے لیں، اعتراف کر کے ان سے معافی مانگ لوں مگر ہمت ہی نہ پڑی۔ 1997ء میں جب ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا تھا کہ سر! بہت دنوںبعد حاضر ہوا ہوں، اس غلطی کی معافی چاہتا ہوں تو جواباً فرمایا: ’’ہم استاد بچوں کی غلطی کرنے سے پہلے ہی انہیں معاف کردیتے ہیں۔ لہٰذا خاطر جمع رکھو۔
شوکت کے حسینی صاحب کے گھر جاتے ہوئے اپنا اخلاق جرم ایک بار پھر بے طرح یاد آیا، سوچا کہ آج جا کر ضرور استاد محترم سے مذکورہ واقع کا ذکر کے معافی طلب کر لوں گا اور جب یہ سوچا تو ان کا اوپر کا درج فقرہ بھی ساتھ ہی یاد آگیا کہ غلطی سے پہلے ہی وہ جب معاف کر دیتے ہیں تو معاف کر چکے ہیں، جرم کے اعتراف کی ضرورت ہی کیا ہے۔ چنانچہ اس دن بھی جب میں شوکت کے ہمراہ ان کی رہائش گاہ پر حاضر ہوا تو معذرت نہ کر سکا۔ ہاں واقعی عطاء اللہ حسینی صاحب بہت بدل چکے تھے،چہرہ مہرہ تو ویسا ہی تھا لیکن صورت انکی اور نورانی ہو چکی تھی۔ گفتگو سے اندازہ ہوا کہ اب تصوف اور روحانیت ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ وہ جو کالج کے زمانے میں وہ فکر مودودیؒ سے متاثر تھے اور ملک میں اسلامی انقلاب کے آرزو مند رہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ جب تک اسلامی جماعت یا جماعتوں کو اقتدار نہیں ملجاتا،شریعت کا نفاذ نہیںہو جاتا، ملک کی منزل کھوٹی ہی رہے گی۔ وہ اسلامی نظام اور اس کے عملی نفاذ پہ بڑے معرکے کی کتاب بھی تصنیف کر چکے تھے۔ اور بھی تصنیفات تھیں لیکن تصوفکی طرف مائل ہونے کے بعد نہ صرف ان کا انداز زیست بدل گیا تھا بلکہ انداز فکر میں بھی نمایاں تبدیلی آگئی تھی۔انہوں نے بتایا کہ ہندوستان میں تصوفہی کے حوالے سے ان کی دو جلدوں پر مشتمل کتاب ’’مکاتیب حسینی‘‘شائع ہو چکی ہے۔ خوش قسمتی سے میں اس کی پہلی جلد ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب سے مستعار لے کر پہلے ہی پڑھ چکا تھااور ان خطوط میں ایسے ایسے دینی نکات پائے تھے کہ دل نے کہا کہ یہ اکتسابی علم نہیں، وہی علم ہے جو خداوند تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے قلب پر القا کرتا ہے۔ دوران گفتگو میں نے عرض کیا کہ سر! ’’مکاتیب حسینی‘‘ کی دونوں جلدیں یہاں بھی چھپنی چاہیں۔ یہ افادۂ عام کے اعتبار سے نہایت قیمتی کتابیں ہیں۔ فرمانے لگے! ’بھائی یہاں کون چھاپے گا‘‘۔
عرض کیا: ’’اگر آپ چاہیں تو اسکا بیڑہ یہ خاکسار اٹھا سکتا ہے‘‘۔
ان دنوںمیں اپنا پبلشنگ ہائوس قائم کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، اس لیے یہ پیش کش میںنے کر دی جسے استاد محترم نے بہ صد مسرت قبول کر لی۔ یہ الگ بات کہ دونوں جلدوں کی کمپوزنگ مکمل ہونے کے بعد حالات نے ایسا رخ اختیارکیا کہ مجھے اپنا پبلشنگ ہائوس بند کرنا پڑ گیا۔ اور یوں’’مکاتیب حسینی‘‘ کی دونوںجلدوں کو اپنے ملک میں دن کی روشنی دیکھنا تاحال نصیب نہ ہو سکا ہے اور کمپوز شدہ مواد بدستورمنتظر اشاعت ہے۔ کیا خدا کا کوئی بندہ کوئی پبلشر ایسا ہے جو ان کی طباعت کا بندوبست کر سکے؟
استاد محترم نے بتایا کہ درس وتدریس سے اب ان کا براہ راست تو کوئی تعلق نہیں رہا البتہ کالج کے احاطے کی مسجد کے وہ نہ صرف متولی ہیں بلکہ امامت اور جمعہ کے وعظ کی ذمہ داری بھی ان ہی کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے درس قرآن کا ایک سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے۔ ہر درس میں جن سورتوںکی تشریح وہ کرتے ہیں، انہیں کوئی صاحب دل شائع کرا کے نمازیوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ عطاء اللہ حسینی کے گھر جا کر میں اور شوکت دونوں ہی حیران ہوئے کہ وہ جو کبھی ان کا چھوٹا سا ڈرائنگ روم ہوتا تھا اب ان کے وسیع کتب خانے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ الماریاں قطار درقطار ایستادہ تھیں اور ان میںموضوعات کے اعتبار سے کتابیں سجی ہوئی تھیں۔ کتاب کا ذوق اس عمر میں ایسا دیکھا کہ جو بھی نئی کتابیں چھپ کر بازار میں آتی ہیں، استاد محترم انہیں خرید لاتے ہیں اور جب تک ان کی مطالعہ مکمل نہ کرلیں، انہیں چین نہیں آتا۔ مطالعے سے ہی انہیں سچی خوشی ملتی ہے۔ راحت کا احساسہوتاہے۔ دوران گفتگو کسی سوال کے جواب میں فرمایا: ’’بھئی یہ جو اقتدار وغیرہ ہے کسی کوشش اور جدوجہد سے ہاتھ نہیں آتا۔ یہ خداوندی تعالیٰ کاانعام ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے‘‘۔
’’تو کیا اسلامی انقلاب ہماری منزل نہیں؟‘‘ میں نے پوچھا۔
’’اسلام میں دعوت و تذکیر ہے۔ ہماری ذمہ داری نیکی کی طرف بلانا اور برائیوں سے اللہ کے بندوں کو بچانا ہے اور وہ بھی حسنِ اخلاق کے ساتھ تبلیغ و تلقین اور نصیحت کا حکم ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر اس کے نتیجے میں معاشرہ بدلتا ہے اور اخلاقی اعتبار سے اس نہج پر آجاتا ہے کہ شریعت کا نفاذ ممکن ہو سکے تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی اسلامی جماعت کو اقتدار بھی عطا کر دیں۔ لیکن یہ اقتدار وغیرہ کوئی ایسی نعمت نہیں جو طلب اور کوشش وغیرہ سے مل سکے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اقتدار اب تک مل نہ چکا ہوتا‘‘۔
استاد محترم کی بات میں وزن تھا اور کوئی دلیل ایسی نہ تھی جس سے ان کے نقطہ نظر کو بے وزن ثابت کیا جا سکے۔ جن ملکوں میں کسی دینی جماعت کو وقتی طور پراقتدارملابھی تو وہ عارضی ثابت ہوا۔ چاہے مصر ہو یا افغانستان۔ اگر منشائے ایزدی نہ ہوتی تو انہیں اقتدار سے بے دخل کرنے کی کس میں جرأت ہوتی۔ استاد محترم کی گفتگو میں جو اصل نکتہ قابل غور تھا وہ یہ کہ ہمیں رب العالمین اور انکے نقطۂ نظر سے بھی معاملات دنیاوی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو اس میں اللہ تعالیٰ ہی سے رہنمائی طلب کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہمیں عقلی تجزیے کی محتاجی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اس قلب پر حقائق کا القاکردیتے ہیں جو حرص و ہوس، بدگمانی وہ بے یقینی سے منّزہ ہو کر آئینے کی طرح شفاف ہو چکا ہو۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں وہ تب تک نہیں اٹھتے جب تک آدمی کا قلب مصفا نہ ہو جائے۔ ان کی دلیل یہ بھی تھی کہ قرون اولیٰ کے تیئس برسوں کے اسلامی اقتدار کے بعد آخر کیا وجہ ہے کہ علما اور صوفیہ نے کبھی اقتدار کی نہ طلب کی اور نہ اس کے لیے کوششیں ہی کیں۔ صوفیہ نے دربار سے اپنا تعلق ہی نہ رکھا اورعلماء حق نے بھی بادشاہوں سے کوئی تعلق رکھا تو نصیحت ہی کی حد تک رکھا۔ قرآن حکیم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کو اقتدارعطا نہیں کیا۔ بیشتر نبیوں کی ذمہ داری دعوت و تذکیر ہی کی رہی۔ ان معدودے چند انبیاء کے جنہیں کسی نہ کسی مصلحت کے تحت حکومت عطا کی گئی۔ قرآن حکیم میں حکومت عطا کرنے کا وعدہ گروہوں کے لیے کیا گیا جو حکومت ملنے کے بعد نماز قائم کریں۔ نماز کیا ہے؟مومن کی معراج۔ تو اسلامی حکومت کا اصل مقصد و منشا بندوں کا اللہ تبارک تعالیٰ سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنا ہے۔ لیکن یہ تو اسی وقت ممکن ہے جب دعوت توحید و تذکیر کے ذریعے معاشرے کے اندر اس کی خواہش پیدا ہو چکی ہو۔ طلب کے بغیر کوئی انعام نہیں ملتا۔ اقتدار بھی ایک انعام ہے جو طلب اقتدار سے نہیں،طلبِ اللہ کے نتیجے میں ملتا ہے۔
ان حکیمانہ نکات کو سمیٹ کر جب ہم واپس آرہے تھے تو میں نے شوکت عابد سے کہا کہ آپ سچ ہی تو کہہ رہے تھے حسینی صاحب بدل چکے ہیں۔ باہر سے تو نہیں اندر سے۔ تبدیلی پہلے باطن ہی میں آتی ہے۔ جب باطن میں آتی ہے تو ظاہر بھی بدل جاتا ہے۔ ہماری کم فہمی یہ ہے کہ ہم باہر کو بدلے میں ساری قوت صرف کر دیتے ہیں اور اسی پر اکتفاکر لیتے ہیں۔ اصل تبدیلی تو وہ ہے جو اندر کو بدل ڈالے۔ خواہ فرد ہو یا معاشرہ؟