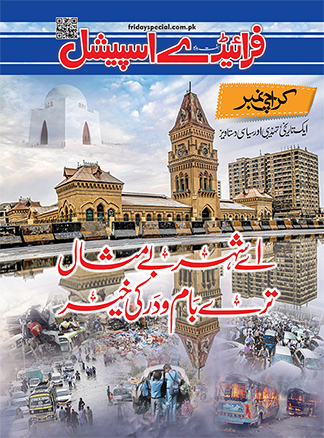سیاہ شیروانی، دبیز شیشوں والی عینک، سر پہ جناح کیپ، ہاتھوں میں چرمی بیگ، ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ… جب بھی انھیں دیکھا، اسی پوشاک، اسی حال میں دیکھا۔ بولنے اور مسلسل بولتے رہنے کی عادت۔ موضوع واحد تحریک پاکستان اور اس تحریک میں بہ حیثیت مقرر و خطیب، بہ حیثیت کارکن ان کی سرگرمیاں۔ اس سے ہٹ کر کبھی کوئی اور گفتگو انھوں نے کی ہی نہیں۔ بہار کے فرقہ وارانہ فسادات اور قیام پاکستان کے بعد ہجرت کرکے سابق مشرقی پاکستان کے چھوٹے سے شہر راج شاہی میں پناہ گزیں ہوئے۔ چائے کی ایک کمپنی میں ملازمت اختیار کی۔ ابا جان اور امی جان سے ان کی دوستی تھی۔ تو واقفیت اُن سے وہیں سے تھی، لیکن پہلی بار ملنا اسی شہرِ ناپرساں میں ہوا۔ ان کی طرح میرا خاندان بھی مشرقی پاکستان کے ناگفتہ بہ حالات سے متاثر ہوکر یہاں منتقل ہوکر جہد للبقا میں مصروف تھا۔ ایک دن امی جان نے کہا: ’’تمہیں لکھنے پڑھنے کا شوق ہے۔ میرے ایک دوست ہیں میاں ظفیر احمد، اُن سے جاکر ملو، اُن کی صحبت میں اُٹھو بیٹھو، تمہارے شوق کو جِلا ملے گی‘‘۔ ان کے دیے ہوئے پتے پر ڈھونڈتا ڈھانڈتا میں میاں ظفیر احمد تک پہنچا۔ کمرے میں اخبارات اور کتابوں کا ڈھیر لگا تھا۔ تعارف کرایا تو فرمایا: ’’اچھا تو تم مسعود کے بیٹے ہو‘‘۔
اور پھر انھوں نے ’’پاکستان کیسے بنا؟‘‘ کی کہانی شروع کردی۔ وہ دن اور بعد کے تمام ایسے دن، جن میں اُن سے ملنا جلنا ہوا، یہ کہانی کبھی ختم ہوئی ہی نہیں۔ پاکستان ان کی سانسوں میں، ان کے سارے وجود میں نس نس میں بسا ہوا تھا۔ اتنے واقعات، اتنے قصے کہ سنتے سنتے ذہن سُن ہوجاتا، اعصاب شل ہوجاتے، جی اوبنے لگتا۔ لیکن وہ بولتے نہ تھکتے۔ اس روز انھوں نے مہربانی فرمائی اور گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں فارغ کردیا۔ چلنے لگا تو ایک مضمون نکال کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ ’’اخبار جہاں‘‘ میں جاکر محمود شام صاحب کو دے آئو۔ میں نے سعادت مندی سے ان کی ہدایت کی تعمیل کی۔ شامؔ صاحب کو مضمون دینے گیا تو انھوں نے مضمون کو سرسری انداز میں دیکھ کر فرمایا: ’’یہ صاحب کہاں ہیں؟ انھیں تو لکھتے رہنا چاہیے۔ اب یہ واقعات بتانے والے کہاں رہے؟‘‘ تب مشرقی پاکستان تازہ تازہ بنگلہ دیش بنا تھا۔ حب الوطنی کا جذبہ اتھاہ مایوسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے واپس جاکے میاں ظفیر احمد صاحب کو، جنہیں ابا امی کی دوستی کے حوالے سے ’’چچا‘‘ کہا کرتا تھا، بتایا کہ شام صاحب ایسے کہہ رہے تھے۔ بہت خوش ہوئے اور ان کے اس فقرے کو ہمیشہ یاد رکھا۔ کئی بار وقفے وقفے سے حوالہ بھی دیا کہ اب ماضی کو یاد کرنے اور یاد رکھنے والے کہاں رہے؟
ان سے طویل مدت تک مشفقانہ رفاقت رہی۔ انھوں نے ہمیشہ اپنا خرد سمجھا اور ہمیشہ حوصلہ افزائی کی۔ وہ جانتے تھے کہ راج شاہی سے لٹ پٹ کر آنے کے بعد کراچی میں ہمارے گھرانے کو کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ میں ٹاور میں گنّے کی مشین پر چچا کا ہاتھ بٹاتا تھا اور جب فرصت ملتی تو وہاں سے ان کے پاس چلا جاتا تھا۔ ایک بات، عجیب سی بات جو میں نے ملنے جلنے کے تمام عرصے میں محسوس کی، وہ یہ کہ انھوں نے کبھی اپنے گھرانے، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں کوئی بات نہ کی۔ اپنی کسی اذیت، کسی دُکھ اور محرومی کا کوئی تذکرہ نہ کیا۔ جب ذکر کرتے تو بس پاکستان اور تحریک پاکستان ہی کا ذکر کرتے۔ اس تذکرے میں بہار کے مسلم لیگ کے رہنما مولانا راغب احسن کا بھی تذکرہ ہوتا جن کے ساتھ ان کی صحبت رہی تھی۔ مولانا نے قائداعظم کو یہ خط لکھا، قائداعظم نے یہ جواب دیا۔ آواز میاں ظفیر صاحب کی باریک سی تھی جو بولتے بولتے بلند ہوجاتی تھی، جوشِ جذبات میں کبھی کبھی منہ سے نکلا ہوا تھوک بھی اُڑ کر ان کی شیروانی کے اوپری حصے کو نم کردیتا، مگر ان کا بیان جاری رہتا۔ اب یاد بھی نہیں ٹھیک سے کہ ان سے کتنی ملاقاتیں ہوئیں، لیکن ہر ملاقات میں میری حیثیت ایک خاموش سامع کی ہوتی تھی اور ان کی خطیب کی۔ ہاں فنِ خطابت کے ماہر تھے۔ سنا تھا کہ بہت اچھا بولتے ہیں اور جب بولتے ہیں تو مجمع دم بخود ہوکر سنتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے بھی ان کی تقریر سننے کا موقع ملا۔ جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ اس تقریر میں انھوں نے بنگالی زبان کے عظیم شاعر رابندر ناتھ ٹیگور اور اردو کے عظیم شاعر علامہ اقبال کی شاعری کا موازنہ کیا تھا اور دونوں کی شاعری کا فرق ایک نہایت خوب صورت تشبیہ سے واضح کیا تھا۔ فرمایا: اقبال کی شاعری زندگی کے مہیب کارخانے کی وہ سیٹی ہے جس کے بجتے ہی کام کرنے والے مزدور آمادۂ عمل، آمادۂ کام ہوجاتے ہیں، اور ٹیگور کی شاعری اس شانت گھر کی مالکہ جیسی ہے جو اپنے تھکے ہارے مرد کا دروازے پر سواگت کرتی ہے اور اپنی محبت بھری مسکراہٹ سے اس کی ساری تھکن دور کردیتی ہے۔ گویا اقبال کی شاعری جدوجہدِ حیات کی، اور ٹیگور کی اس جدوجہدِ حیات سے تھک جانے والوں کو محبت، سکون اور شانتی دینے والی شاعری ہے۔ دونوں ضروری ہیں۔ مجھے اس تشبیہ نے بہت متاثر کیا اور میں نے جانا کہ ان کا ادبی وژن وسیع و فراخ ہے اور اس میں کوئی مذہبی عصبیت نہیں پائی جاتی۔
جن دنوں وہ ’’جنگ‘‘ اخبار سے منسلک تھے، میں وہاں کسی کام سے گیا تو ان سے بھی ملنے چلا گیا۔ میر خلیل الرحمن مالک جنگ اخبار کا قصہ انھوں نے سنایا کہ میں اپنا مضمون انھیں دینے گیا تو انھوں نے کہا: ’’ظفیر صاحب ملک تو آدھا رہ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے پڑھنے والوں کے اندر ملک سے محبت کا جذبہ پیدا کروں اور اس میں میرا اخبار اپنا کردار ادا کرے، تو کیوں ناں ’’ہم سب پاکستانی ہیں‘‘ کے عنوان سے ایک صفحہ نکالا جائے جسے آپ ہی مرتب کیا کریں‘‘۔ میں نے رضامندی ظاہر کی تو یہ سلسلہ شروع ہوگیا۔ بہت عرصے تک یہ صفحہ نکلتا رہا۔ پھر جانے کیا واقعہ ہوا کہ میاں ظفیر احمد ’’جنگ‘‘ سے نکل کر ’’نوائے وقت‘‘ میں کالم نگاری کرنے لگے۔
نوّے کی دہائی میں اس خاکسار پر گہری مذہبیت طاری ہوئی۔ پابندیٔ شریعت کی حالت اور کیفیت میں ان سے دو ایک ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک دن معروف صحافی اور مصنف و محقق ضمیر نیازی صاحب کا فون آیا کہ بھئی آج نوائے وقت میں میاں ظفیر احمد کا تمہارے بارے میں ایک کالم چھپا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھ پر انھیں کالم لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آگئی؟ ڈپارٹمنٹ کی سیمینار لائبریری میں جاکر اخبار میں ان کا کالم دیکھا تو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ انھوں نے اس عاجز کی مذہبیت کو موضوع سخن بنایا تھا۔ کالم کا لب و لہجہ ایک مشفق بزرگ جیسا تھا جسے اپنے کسی خرد سے مخاطب ہونا بالواسطہ طریقے سے اور اسے نصیحت کرنا اور مشورہ دینا مقصود ہوتا ہے۔ اس واقعے کے مدتوں بعد جب میں جزوقتی طور پر ’’نوائے وقت‘‘ سے وابستہ ہوا اور یونیورسٹی سے فرصت پاکر اخبار کے دفتر جانے لگا تو وہاں ان سے ملاقاتیں رہنے لگیں۔ مجید نظامی مرحوم ان سے بہت متاثر، ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ’’نوائے وقت‘‘ ویسے بھی دو قومی نظریے کا پُرجوش مبلغ اخبار تھا اور میاں ظفیر احمد کے مزاج سے ’’جنگ‘‘ اخبار سے کہیں زیادہ مناسبت رکھتا تھا۔ حکومت نے تحریکِ پاکستان میں حصہ لینے والے بزرگوں کو گولڈ میڈل دینے کا سلسلہ شروع کیا تو مجید نظامی ہی کی سفارش پر انھیں بھی گولڈ میڈل عطا کیا گیا۔ وہ کبھی اپنا کالم دینے اور کبھی ویسے ہی ملنے ملانے نوائے وقت کے دفتر واقع ڈیفنس آجایا کرتے تھے۔ اگر میں دفتر میں موجود ہوتا تو میری ہی میز کے سامنے تشریف فرما ہوجاتے اور پھر تحریک پاکستان، قائداعظم، مولانا راغب احسن، کلکتہ میں مسلم لیگ کی سرگرمیاں اور وہی پرانے دھرانے قصے شروع ہوجاتے۔ میں سنتا جاتا، اثبات میں سر ہلاتا جاتا۔ کبھی کبھی یہ بھی سوچتا کہ چچا ماضی میں کیوں زندہ ہیں؟ یا ماضی کیوں ان کے اندر اٹک کر رہ گیا ہے کہ نکلتا ہی نہیں۔ مجال ہے جو کبھی انھوں نے حالیہ سیاست پر کوئی تبصرہ کیا ہو، کبھی کسی زندہ و موجود سیاست داں یا سیاسی جماعت پر گفتگو کی ہو۔ وہی ماضی کی باتیں… ماضی جو بیت چکا تھا، کھو چکا تھا، تاریخ کا حصہ بن چکا تھا… مگر وہ ماضی میاں ظفیر احمد کی شیروانی سے، ان کے حافظے سے، ان کے سارے وجود سے ایسے چمٹا، ایسے لپٹا ہوا تھا کہ چھڑائے نہیں چھوٹتا تھا۔ ان کے اردگرد جو لوگ تھے، جو معاشرہ تھا وہ لمحۂ موجود میں، ’’آج‘‘ میں سانسیں لیتا تھا، مڑ کر پیچھے دیکھنے اور بیتے بِتائے دنوں کو یاد کرنے پر تیار نہ تھا، یا اس کی فرصت نہ پاتا تھا، لیکن لے دے کر کروڑوں کی آبادی میں ایک میاں ظفیر احمد ہی رہ گئے تھے جو یہ بھولنے کے لیے تیار ہی نہ تھے کہ پاکستان بنا کیسے اور کن حالات میں بنا۔ جس ماضی کو قوم بھول چکی تھی، اسے میاں ظفیر احمد نے یاد رکھا ہوا تھا۔ اس ماضی سے انھیں عشق تھا۔ وہ قربانیاں جو اس ملک کے قیام کے وقت دی گئیں، وہ سرگرمیاں اور دوڑ بھاگ جو اس کو قائم کرنے کے لیے کی گئیں، فقط یہی ایک راگ تھا جسے الاپتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی تو شبہ ہوتا ایسا کہ میاں صاحب کا بس نہیں چلتا کہ اس ماضی کو زندہ کردیں، اسی طرح کہ نئے سرے سے تحریکِ پاکستان چلے، پھر سے پاکستان بنے اور وہ اس تحریک میں دامے، درمے، قدمے، سخنے اسی طرح شریک ہوں جیسے سن چالیس کی دہائی میں ہوئے تھے۔ لیکن بھلا ایسا کیسے ممکن تھا… اور ایسا ہوا بھی کیا تھا! اور جب نہیں ہوا تھا اور نہیں ہوسکتا تھا تو اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا کہ میاں ظفیر احمد پاکستان اور تحریکِ پاکستان کا راگ الاپتے رہیں۔ سیاست دان، حکمران، بیوروکریسی، طالع آزما جرنیل صاحبان، تجار حضرات، ملازم پیشہ لوگ سب مل کر پاکستان کو لوٹتے کھسوٹتے رہیں۔ بدعنوانیوں اور بدمعاملگیوں کا بازار گرم کیے رکھیں… اور اس ساری ہیر پھیر، لوٹ مار اور مارا ماری سے بے نیاز، الگ تھلگ ایک شخص شیروانی پاجامے میں ملبوس، دبیز شیشے والی عینک لگائے اپنے پورے وجود سے اپنے حافظے میں جمع شدہ سارے لفظوں اور جملوں سے بس ایک ہی کام لے: پاکستان اور تحریک پاکستان کا قصہ اور چرچا۔ رویہ ایسی بے نیازی کا جیسے جس جدوجہد اور قربانیوں سے یہ ملک بنا تھا اور جس کی تفصیل بتاتے وہ نہ تھکتے تھے، اس ملک میں لوٹ کھسوٹ کا جو بازار گرم تھا، اس کی انھیں خبر ہی نہ ہو۔ کبھی میں نے اُن کے منہ سے کسی پارٹی، کسی سیاست داں کی برائی سنی ہی نہیں۔ کسی پر تنقید کرتے، نہ کسی پر نکتہ چینی کرتے۔ حال فی الحال کی سیاست جس پر تبصرہ کرنا ہمارا قومی مشغلہ ہے اس میں انھیں دل چسپی لیتے دیکھا ہی نہیں۔ کبھی کبھی جی چاہتا تھا ان کی شیروانی کے دامن کو پکڑ کر کھینچوں اور انھیں جھنجھوڑ کر نیند سے جگادوں یہ کہہ کر کہ ’’چچا پاکستان بن چکا ہے، اور اب تو اسے بنے ہوئے بھی نصف صدی ہونے کو آئی ہے۔ اپنے بچے کھچے پاکستان کو بھی تو ایک نظر دیکھ لیجیے۔ کبھی اس کی بات بھی تو کیا کیجیے‘‘۔ لیکن میں ان کی حقیقی کیفیات اور ان کے جذبات سے بے خبر تو ہوسکتا تھا لیکن بے ادب تو نہ تھا کہ ایسا کرتا۔
بس اور ویگن بدل بدل کر وہ نوائے وقت کے دفتر آتے رہے کہ گاڑیاں، کاریں اُن کے پاس تھیں جن کا اس ملک کو بنانے میں کوئی حصہ نہ تھا۔ کوٹھیوں اور بنگلوں میں وہ رہتے تھے جنھیں کچھ اور تو اس ملک کی بابت نہیں معلوم تھا لیکن اس ہنر میں ضرورت مہارت تھی کہ کاروبار کو کیسے چمکایا جاتا ہے اور اچھی سرکاری ملازمت کو آمدنی کا ذریعہ کیسے بنایا جاتا ہے۔
میاں ظفیر احمد کی، میرے منہ بولے چچا کی بس اتنی سی کہانی ہے۔ آگے کے جو واقعات ہیں ان میں بھی بس یہی پاکستان اور تحریک پاکستان کی رٹ ہے۔ اب اس واحد سبق کو کیا دہرانا۔
ایک دن کسی واقف کار، کسی شناسا سے فون پر اطلاع ملی کہ میاں ظفیر دنیا میں نہیں رہے۔ بھاگا بھاگا گلشن معمار ان کے گھر پہنچا۔ جنازہ بہت بڑا نہ تھا، پچاس پچھتر لوگ ہوں گے جنہوں نے میت گاڑی پر انھیں قبرستان تک پہنچایا۔ انھیں کھدی ہوئی زمین کی آغوش میں سلایا گیا اور جب منوں مٹی ڈال کے ان کی قبر پر ہم واپس آئے تو رستے میں اپنے احساسات کو ٹٹولتے ہوئے میں نے اپنے اندر ایک قلق، عدم اطمینان پایا کہ اب کوئی آدمی بھی تو ایسا نہیں رہا جو بلاتکان اس ملک اور اس قوم کے ماضی کو یاد کرے۔ ایک آخری آدمی تھا سو وہ بھی رخصت ہوا۔ اللہ بس، باقی ہوس!
nn