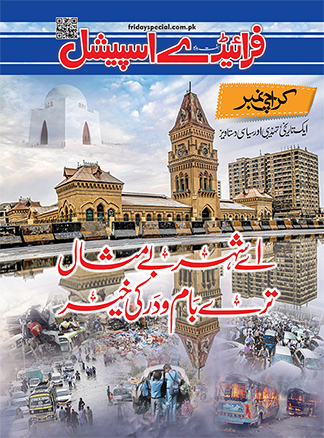زبان دانی کی کلاس میں مضمون لکھنے کے لیے میں نے کوئی موضوع دیا۔ جانتا تھا کہ طلبہ و طالبات جو مضامین لکھ کر لائیں گے، ان میں املا و انشا کی اتنی غلطیاں ہوں گی کہ صفحوں کے صفحے سرخ قلم سے سرخا سرخ ہوجائیں گے، جس کے بعد انھیں یہ سننا ہوگا کہ مطالعہ کیے بغیر اور اچھے ادیبوں اور انشا پردازوں کی کتابیں پڑھے بغیر انھیں کبھی لکھنا نہ آسکے گا۔ اس قسم کی تقریریں کرتے ہوئے، کتب بینی کے فوائد پر روشنی ڈالتے ہوئے مجھے پچیس چھبیس برس ہوچکے تھے، ان کے نتائج مشکل ہی سے خوش گوار نکلے ہوں۔ طلبہ و طالبات نہایت سنجیدگی اور انہماک سے اس قسم کی نصیحتیں اور فہمائشیں سنتے ہیں اور گھر پہنچتے پہنچتے بھول بھال جاتے ہیں۔ بُرا ہو میری عادت کا، پھر بھی باز نہیں آتا۔ ایک بار یہ تجربہ بھی کیا کہ مطالعے کی عادت ڈالنے کے لیے اپنے کتب خانے سے افسانوں اور ناولوں کو اپنے شاگردوں میں تقسیم بھی کیا اور تجربے کی ناکامی کے بعد اگلی مرتبہ نئے طلبہ و طالبات کو لے کر نیشنل بک فاؤنڈیشن کے دفتر گیا، وہاں سو سو روپے میں ممبر شپ دلوائی، رعایت پر انھیں وہیں سے شفیق الرحمن، کرنل محمد خان، بانو قدسیہ، اشفاق احمد وغیرہ کی کتابیں بھی خریدوائیں کہ اس طرح انھیں آہستہ آہستہ کتابیں پڑھنے کی شاید عادت پڑ جائے گی۔ لیکن نتیجہ۔۔۔ ڈھاک کے تین پات۔ تو اُس دن جس کا اوپر میں نے ذکر کیا، کوئی عنوان دے کر انتظار میں بیٹھ رہا۔ کلاس کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اکثر مضامین کا ڈھیر میرے سامنے میز پر لگ چکا تھا۔ دو تین صفحے لکھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ چوں کہ مضامین وہیں چیک کرنے کا وقت نہ رہا تھا اس لیے پلندہ اُٹھا کر گھر لے آیا۔ رات کسی وقت چیک کرنے بیٹھا تو صورت حال توقع کے عین مطابق تھی۔ انشا تو دور کی بات، املا کی ایسی فاش غلطیاں تھیں کہ پہلی بار آدمی پڑھے اور یہ بھی معلوم ہو کہ یہ ایم اے کے طالب علموں کی تحریریں ہیں تو تمام اسکولوں پر تالے ڈال دینے کی سفارش کرے کہ ان غلطیوں کی اصلاح تو اسکول ہی میں ہوجانی چاہیے تھی، اگر وہاں نہ ہوسکی تو اسکول کے اساتذہ یا استانیوں نے کیا سکھایا؟ (ایک معمولی سی مثال: ایک طالبہ نے آصف زرداری کا نام ایک مرتبہ ’’ع‘‘ سے عاصف زرداری لکھا۔ حیران ہو کر پوچھا: ’’بی بی! ملک کے صدر کا نام تک لکھنا نہیں آتا! کیا ٹیلی وژن کے ٹیکر بھی نہیں پڑھتیں کہ روزانہ بیسیوں بار ٹیکر پر آتا رہتا ہے‘‘۔ جو، جواب آیا اسے نقل کرنا ملک کے تعلیمی نظام اور اس کی زبوں حالی کا منہ چڑانا ہے۔)
بات دور جا پڑی۔ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس رات مضامین چیک کرتے کرتے اچانک دو صفحات ایسے نکل آئے جیسے حبس اور گھٹن کے بعد یک بیک بارش سی ہونے لگے۔ یہ دو صفحے کیا تھے، نہایت خوش خط۔۔۔ جیسے لفظوں میں، حرف حرف میں موتی سے پرو دیے گئے ہوں۔ جب سے بال پوائنٹ کا استعمال عام ہوا ہے اور تختی اور سلیٹوں پر خوش خطی کی مشق کرانے کا چلن طالب علموں سے متروک ہوا ہے، ہینڈ رائٹنگ پر طلبہ و طالبات کی ایسی افتاد ٹوٹی ہے کہ امتحانی کاپیاں اور عام مضامین میں ان کے لکھے ہوئے کو پڑھنا اساتذہ کے لیے تزکیہ نفس کا ذریعہ بن گیا ہے۔ تو جب یہ دو صفحے خوش نما، خوش تحریر لفظوں سے مزین سامنے آئے تو میں ٹھٹھک کر رہ گیا۔ پھر جو مضمون پڑھا تو مافی الضمیر کے بیان میں صفائی، محاوروں کا استعمال اور خیالات کا اظہار ہر قسم کے الجھاؤ اور ژولیدگی سے پاک صاف۔۔۔ پڑھتا جاتا تھا، حیران ہوتا جاتا تھا۔ جب پڑھ چکا تو ذہن میں وہی فرسودہ سا مصرع گونجا کہ جسے دہراتے ہوئے بھی مزہ نہیں آتا، لیکن ہے اتنا سچا اور واقعی کہ کوئی اور مصرع اس صورت حال پر منطبق بھی مشکل ہی سے ہوتا ہے کہ
ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی
اگلے دن میں نے بھری کلاس میں رجسٹر اور مضامین کا پلندہ میز پر رکھتے ہوئے بآوازِ بلند پوچھا:
’’یہ خوشبو کون ہے؟‘‘
مضمون نگار طالبہ کا نام یہی تھا۔ غالباً دوسری یا تیسری صف سے ایک چھوٹی سی بہ ظاہر منحنی سی طالبہ نے ہاتھ بلند کیا۔ میں نے اسے قریب بلایا، کلاس کے سامنے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے نہایت توصیفی کلمات کہے اور شاید کلاس کو شرمندہ کرنے یا ترغیب دلانے کے لیے وہ مضمون پڑھ کر سنایا بھی۔ زبان دانی کی یہ کلاس چلتی رہی۔ دوسرے لڑکے لڑکیوں کی غلطیوں سے، فروگزاشتوں سے پُر مضامین سرخ قلم سے سرخا سرخ ہوتے رہے اور خوشبو اپنے مختصر مختصر مضامین سے مجھے حیران اور کبھی مسرور کرتی رہی۔ سمسٹر ختم ہوا۔ امتحانات میں سب سے زیادہ نمبر بھی ظاہر ہے خوشبو ہی کے آئے۔ بات آئی گئی ہوگئی۔
شاید کئی سال بعد ایک رات موبائل پر ایک ایس ایم ایس روشن ہوا۔ دو تین فقروں میں یہ افسوس ناک اور دل خراش اطلاع دی گئی تھی کہ میرے والد رفیق احمد نقش کا انتقال ہوگیا ہے۔ اطلاع دہندہ کا نام خوشبو تھا۔ رفیق احمد نقش سے واقفیت تو پرانی تھی لیکن یہ سمجھ میں نہ آیا کہ خوشبو کا رفیق سے کیا رشتہ ہے؟ اگر خوشبو، رفیق کی صاحبزادی تھیں تو یہ بات کبھی رفیق نے کیوں نہ بتائی اور خود خوشبو نے اس کا تذکرہ بھی کبھی کیوں نہ کیا؟ میں نے فوراً ہی جوابی میسج کیا۔ پوچھا: ’’کیا تم وہی خوشبو ہو، میری طالبہ؟‘‘ فوراً ہی جواب آیا ’’جی سر وہی‘‘۔ پھر پوچھا: ’’تو یہ بات کبھی تم نے یا رفیق نے بتائی کیوں نہیں؟‘‘ ایک غیر مطمئن کردینے والا جواب آیا: ’’پاپا نے کہا تھا یونی ورسٹی میں داخلہ تو لے رہی ہو، وہاں کے بہت سے ٹیچرز میرے دوست ہیں، اپنے میرٹ ہی پر اُن سے معاملہ رکھنا۔ میرا نام یا حوالہ کبھی نہ آنے پائے‘‘۔
یہ جواب اچھا تو لگا کہ ہمارے ملک میں جان پہچان، سفارش اور اثر رسوخ کی بری روایت ایسی پڑچکی ہے کہ اگر کوئی آدمی اصولی بنیاد پر اپنے بچوں میں اپنی صلاحیت پر اعتماد پیدا کرنے اور اپنی ہی محنت و مستقل مزاجی سے آگے بڑھنے کی خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے اور وہ ایسی کوئی ہدایت کرتا ہے تو یہ بڑی قابلِ رشک اور لائقِ تقلید بات ہے۔ لیکن جو بات اس نصیحت میں کھٹکی وہ یہ تھی کہ مرحوم نے اس نصیحت میں نہایت خاموشی سے بنا کہے یونی ورسٹی کے اساتذہ پر بداعتمادی کا بھی تو اظہار کردیا تھا۔ گویا اس تنبیہ میں ایک پوشیدہ اشارہ، جس کا ممکن ہے شعوری احساس خود رفیق مرحوم کو بھی نہ ہو کہ میں اور دیگر اساتذہ یہ جاننے کے بعد کہ خوشبو جانے پہچانے ادیب، ماہر لسانیات، شاعر رفیق احمد نقش کی صاحبزادی ہیں اس لیے امتحانی نمبروں میں کسی حق کے بغیر، کسی صلاحیت کے بنا ہی اسے امتیازی نمبروں سے نواز دیں گے، اور پھر یہی نہیں، یہ اس تربیت اور ذہن و کردار سازی پر بھی تو عدم اعتماد تھا جو رفیق نے ایک اصول پسند باپ کی حیثیت سے اپنی نہایت نیک اور باصلاحیت بیٹی کی کی تھی۔ کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ سادہ دل اور نیک نفس باپ کو اگر کہنا ضروری ہی تھا تو بس اتنا کہہ دیا ہوتا کہ بیٹی! تمہارے اکثر اساتذہ مجھے جانتے ہیں لیکن اس بنیاد پر اُن سے کسی رعایت کی توقع نہ رکھنا۔ باصلاحیت وہی ہوتا ہے جو اپنی صلاحیت سے خود کو منواتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ خوشبو جیسی باصلاحیت بیٹی اپنے باپ کے نام کی لاج رکھتی اور یوں مجھے مدتوں اس حیرت اور تجسس میں مبتلا نہ رہنا پڑتا کہ اپنے خاکستر میں ایسی چنگاری کہاں سے آگئی۔
جو ادیب اور شاعر حضرات رفیق احمد نقش کو جانتے ہیں انھیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ رفیق نے اپنی زندگی علم اور کتاب کی نذر کردی تھی۔ ان کا اوڑھنا بچھونا کتابیں تھیں، ان کے دوستوں کے حلقے میں سبھی لکھنے پڑھنے کا شوق رکھنے والے لوگ تھے۔ یہ سب کے سب رفیق پر جان چھڑکنے والے تھے، اور خود رفیق بھی دوستوں کے بغیر خود کو ادھورا پاتے تھے۔ ان کے دن اور شامیں، یہاں تک کہ بسا اوقات راتیں بھی دیر تک ان ہی دوستوں کے درمیان گزرتی تھیں۔ ایک ایسی ہی رات کا دل گداز واقعہ ان کے کسی دوست نے بیان کیا کہ رفیق بہت دیر سے گھر پہنچے، کیا دیکھا کہ اہلیہ محترمہ سیڑھیوں کے پاس کرسی ڈالے میاں کی راہ تکتے تکتے تھک ہار کر بے خبر سو رہی ہیں۔ رفیق کو دھچکا لگا۔ راوی سے واقعے کے تذکرے کے بعد یہ بیان بھی مذکور ہے کہ رفیق نے کہا: میں نے خود کو کبھی معاف نہیں کیا۔ راوی بھی عجب ستم ظریف۔۔۔ لکھتا ہے: خود کو معاف نہ کرکے بھی انتظار کی راہ دکھانے میں کوتاہی پھر بھی نہ ہوئی۔ میں سوچتا ہوں ایک دل میں ایک وقت میں ایک ہی عشق کی گنجائش ہوتی ہے شاید۔ شوہر ادیب و محقق ہو یا کاروباری اور بڑا افسر۔۔۔ اپنے کام سے عشق، ایسا عشق کہ خود کو فنا کیے بغیر گوہرِ مقصود ہاتھ نہیں آتا۔ چناں چہ میں نے ادیبوں اور شاعروں، تاجروں، افسروں، سیاست دانوں، وکیلوں، اداکاروں، کھلاڑیوں سب کا یہی حال دیکھا کہ زندگی میں اعتدال و توازن نام کو نہیں۔ بیوی کا دوسرا نام انتظار ہے، خدمت ہے، پابندی اور بے جا اُمیدیں اور توقعات ہیں۔ ایثار و قربانی بیوی کرتی ہے۔۔۔ کامیابی، فتوحات اور سرخروئی میاں جی کے حصے میں آتی ہیں۔ بیوی کی تشفی کے لیے فقط یہی ایک کلغی کہ کامیاب آدمی کی زوجہ محترمہ ہیں، بہت کافی ہے۔ بیویوں کی اس اَن کہی شکایت کو رفع کرنے ہی کے لیے بہ طور دلاسا یہ قولِ فیصل گھڑا گیا کہ ’’ہر کامیاب مرد کے عقب میں ایک عورت ہوتی ہے‘‘۔ (کسی طنز نگار نے یہ کہہ کر اس ڈھارس کا بھی گلا گھونٹ دیا کہ ضروری تو نہیں کہ وہ عورت بیوی ہی ہو)
رفیق ایک سچا، کھرا، اصول پسند، نہایت صاف گو انسان تھا۔ یہ بھی ہے کہ سچائی، کھرا پن، اصول پسندی و صاف گوئی جیسے مقوی پھل عموماً کڑواہٹ لیے ہوتے ہیں۔ تلخی ایسی ہوتی ہے کہ اندر تک اُترتی چلی جاتی ہے، بھالا بن کر سینے میں پیوست ہوجاتی ہے۔ مدتوں تک قطرہ قطرہ خون رستا رہتا ہے۔ رفیق کی بابت دوست احباب جب بھی پرانی بھولی بسری یادیں تازہ کرنے بیٹھتے ہیں، ہر ایک کی پوٹلی میں کوئی نہ کوئی اُس کی صاف گوئی اور کھرے پن کا چبھتا ہوا واقعہ ہوتا ہے۔ رفیق کی علمیت، زبان دانی، وسعتِ مطالعہ، علم دوستی اور دوست نوازی کی قائل و گھائل شخصیات میں ایسی ایسی قدآور ہستیاں علم و تحقیق کی دنیا کی ہیں کہ حیرت تو ہوتی ہے، رشک بھی آتا ہے کہ ڈاکٹر گیان چند، مشفق خواجہ، محمد خالد اختر، نیّر مسعود، انتظار حسین، یہ وہ ادیب و محقق ہیں جو مانتے ہی نہیں جب تک جادو سر چڑھ کر نہ بولے۔ ڈاکٹر گیان چند اپنی وقیع تحقیقی کتاب ’’اردو کی ادبی تاریخیں‘‘ کے بارے میں یہ اعتراف فراخ دلی سے کریں کہ ’’ایک قابل نوجوان کالج لیکچرار رفیق احمد نقش نے میری ادبی تاریخوں کی کتاب پر پروف ریڈنگ کرتے وقت نشان دہی کی کہ (لفظ ’’وطیرہ‘‘ کا) صحیح املا ’’وتیرہ‘‘ ہے‘‘۔ اور پھر یہ فرمائیں:
’’زمانۂ طالب علمی سے تاحال میں نے کسی دوسرے لفظ کے ہجے غلط نہیں لکھے‘‘۔
یا مشفق خواجہ جو بڑے بڑے ادیبوں اور محققوں کی تحقیقی اور لسانی غلطیاں نکالنے کی اردو دنیا میں بے مثال شہرت رکھتے تھے، وہ ’’کلیاتِ یگانہ‘‘ کے دیباچے میں یہ تسلیم کریں کہ ’’میں نے کوشش کی کہ ’’کلیاتِ یگانہ‘‘ میں زبان و بیان کی کوئی غلطی پروف ریڈنگ میں نہ رہے۔ جو دو چار غلطیاں میری گرفت میں نہ آسکیں وہ رفیق احمد نقش صاحب کی دُوررس نظروں سے نہ بچ سکیں۔ اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں‘‘۔ تو رفیق کا زبان و بیان اور املا و انشا کی باریکیوں پر عبور اور دقتِ نظری کا قیاس کیا جاسکتا ہے۔
اس خاکسار نے بھی ایسے ہی ایک واقعے سے رفیق کی مذکورہ امتیازی حیثیت کو پہچانا۔ خواجہ صاحب (مرحوم) کے گھر اتوار کے اتوار اہلِ علم کی کھلی نشست ہوتی تھی، میرا جب بھی جانا ہوا ایک نوجوان کو دیکھتا تھا جس میں کوئی بات متوجہ کرنے والی پاتا ہی نہ تھا۔ مستزاد یہ کہ نوجوان نے کم سے کم میرے سامنے مشکل ہی سے کبھی گفتگو میں حصہ لیا ہو۔ اب وہ جو حضرت علیؓ کا قولِ مبارک ہے کہ ’’بولو کہ پہچانے جاؤ‘‘۔ خاموشی اور چپ کا معاملہ یہ ہے کہ ایک پردہ ہے جس میں علم بھی چھپا ہوتا ہے، جہل بھی۔ کوئی اپنی خاموشی کا پردہ چاک ہی نہ کرے تو پتا کیسے چلے کہ علم و تہذیب کے کس مقام سے مخاطب ہے، یا نرا جاہل کا جاہل ہے۔ تو خواجہ صاحب نے جب تعارف کرایا کہ یہ رفیق احمد نقش ہیں، نہایت عالم فاضل نوجوان ہیں۔۔۔ تو میں نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی بات ہوگی ہی، ورنہ خواجہ صاحب دل رکھنے کے لیے خود علم و فضل سے مذاق روا نہیں رکھتے۔ پھر اِدھر اُدھر کی ادبی تقریبوں میں بھی رفیق سے کئی ملاقاتیں ہوئیں، لیکن اس کی شخصیت کا کوئی گہرا تاثر مرتب نہ ہوا۔ وہ کسی قدر پستہ قامت، سفید رنگت، چہرے کے کھلتے ہوئے نقوش، کڑھے ہوئے بال، شلوار قمیص میں جب بھی ملے عام سے ہی نوجوان لگے، گمان سا ہوا کہ شعر و ادب کے شوقین ہوں گے، اور شوق کی سرحدیں سنجیدگی سے جاملی ہوں گی۔ کیا پتا آتشِ شوق بھڑکانے کو خواجہ صاحب نے تعریف و توصیف کی ہوا دی ہو۔
ہاں اس دن دوپہر کا وقت۔۔۔ خوب یاد ہے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف رفیق احمد نقش تھے۔ کہنے لگے: آج کل انجمن ترقی اردو کے تحقیقی رسالے ’’اردو‘‘ کے مقالات کی نگرانی اور حروف چینی (پروف ریڈنگ) پر مامور ہوں۔ آپ کا مقالہ ’’کوہ نور‘‘ کے ایڈیٹر ہرسکھ رائے کے بارے میں دیکھ رہا تھا، اس میں یہ جو لفظ آپ نے لکھا ہے (وہ لفظ اب یاد نہیں) اس کا درست املا یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے۔ یہ کہہ کر رفیق نے فون پر ہی یہ حروف دہرا کر لفظ کا صحیح املا بتایا۔ مجھے حیرت سی ہوئی۔ دل میں سوچا: بھائی! یہ صاحب تو چھپے رستم نکلے۔ میں نے ذرا بھی مزاحمت نہ کی۔ عرض کیا: رفیق صاحب! وہی صحیح املا ہوگا جو آپ فرما رہے ہیں۔ اسے درست کردیجیے۔ اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ یوں معلوم ہوا کہ رفیق زبان دانی سے اپنی گہری رفاقت کا نقش دوسروں پر مرتب کرنے میں عجلت یا جلد بازی نہیں کرتے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسا ہی نقش دیرپا بھی ہوتا ہے۔
رفیق سے میری کبھی گہری قربت یا رفاقت نہیں رہی۔ ملاقاتیں بھی کم کم ہی ہوئیں۔ وہ میرپورخاص سے کراچی آئے تھے۔ کہیں سے نہ لگتے تھے کہ آرائیں ہیں۔ لب و لہجہ میں بھی پنجابیت کی خوبو نہ تھی۔ ان کی ذات اور حالات سے واقفیت بھی ان کی وفات کے بعد ان مضامین اور رسالہ ’’روایت‘‘ کے ان پر خصوصی شمارے کے مطالعے سے ہوئی، اور یہ خاکہ لکھنے کا خیال بھی ان کے ادبی دوستوں کے تاثراتی مضامین پڑھ کر ہی آیا۔ چوں کہ میری زندگی کا بڑا حصہ ادیبوں، شاعروں اور لکھنے پڑھنے سے شغف رکھنے والوں کے درمیان ہی گزرا ہے، اس لیے یہ جو ادیب اور شاعر یا لکھنے لکھانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے مزاج، موڈ، عادات و کیفیات، یہاں تک کہ معاملاتِ دینی و دنیوی سے اچھی طرح آشنا ہوں۔ ان ہی مشاہدوں کی بنا پر اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ نہایت مختصر سی عمر میں رفیق نے اپنے عقیدت مندوں کا جیسا حلقہ بنالیا تھا، ویسا حلقہ ان کی عمر میں کسی اور ادیب کا شاید ہی کوئی اور ہو۔ وجہ سادہ سی یہ تھی کہ ادبی، علمی سرگرمی محض ان کا ذاتی شوق کبھی نہیں رہا، وہ اسے عمومی اجتماعی سرگرمی سمجھتے تھے یا اسے ایسا ہی دیکھنے کے آرزومند تھے۔ چناں چہ اپنے دوستوں سے علمی ادبی معاملات میں جیسی جانثاری اور دردمندی ان کے اندر تھی، دوسرے ادیبوں میں مشکل ہی سے پائی۔ زبانی کلامی مشورہ، رہ نمائی اور مدد و معاونت کرنا تو بے حد آسان ہے، خلوص اور ایثار کا پتا چلتا ہے جب کسی علمی ضرورت مند کے لیے آدمی اپنے کتب خانے کے دروازے کھول دے، کوئی تحقیق کرنے والا طلب کسی کتاب کی رکھتا ہو تو اس کے لیے رقم خرچ کرکے کتاب کی نقل تیار کرکے اسے فراہم کردی جائے۔ کسی علمی تحقیقی کام یا ذمے داری پر مامور کیا جائے تو پوری تن دہی اور محنت و انہماک کے ساتھ اس طرح اسے انجام دیا جائے کہ حق ادا ہوجائے۔ رفیق کی بابت یہ گواہی اتنے لوگوں نے دی ہے کہ ان کی شخصیت کا یہ پہلو کم از کم میرے نزدیک مسلمہ حیثیت اختیار کرگیا ہے۔ پھر معاملہ ادب کا ہو، ادبی تحقیق یا لسانیات کا۔۔۔ کسی مصلحت، مداہنت، سمجھوتا یا سود و زیاں کے حساب کتاب سے بلند ہوکر ہر حال میں سچائی اور حق گوئی سے جڑے رہنا ایسا وصف ہے جس کی مثال اردو کی ادبی اور علمی دنیا میں بھی ملتی تو ہے مگر ذرا کم کم۔ یہ سچائی بھی علم اور ادب سے غیر مشروط وابستگی کے بغیر ممکن نہیں۔ معاشرے کا چلن اور رنگ ڈھنگ ایسا ہوگیا ہے کہ معاملات میں جو خرابیاں زندگی کے دوسرے شعبوں میں در آئی ہیں، علم و ادب کا شعبہ بھی ان سے محفوظ نہیں رہا۔ ہر دو کو بھی یار لوگوں نے شہرت طلبی اور دنیاوی کامیابیوں کا زینہ بنالیا ہے۔ اور جب علم و ادب مقصود بالذات نہ ہوں تو پھر رشک و حسد، مقابلہ و مسابقت، دوسرے کو کہنی مار کر اور اڑنگی لگا کر کسی نہ کسی طرح خود کو آگے بڑھانے اور اپنے حق سے زیادہ وصول کرنے کا رویہ اور رجحان بھی عمومی مزاج بن گیا ہے۔ چناں چہ سیاست کے میدان کی طرح جامعات، علمی و ادبی اداروں اور ادبی گروہ بندیوں کو بھی اسی مزاج نے زہر آلود اور ناقابلِ برداشت بنادیا ہے۔ رفیق احمد نقش جس کی اصل جگہ اور مقام کوئی یونی ورسٹی اور کوئی اعلیٰ تعلیمی درس گاہ ہونی چاہیے تھی، اس لیے نہ ہوسکی کہ اس کی علمیت، وسعتِ مطالعہ اور علم و ادب سے اس کا اخلاص، المختصر اس کا ہنر ہی عیب بن گیا۔ ہاں اب ہمارے چاروں طرف زندگی کے اکثر و بیشتر شعبوں میں جعلی سکوں کا راج ہے، یہ کھوٹے سکے تعداد میں اتنے زیادہ ہیں اور اس طرح چھا گئے ہیں کہ جو دو چار اصلی سکے ہیں، انھیں چلنے ہی نہیں دیتے۔ اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے، کسی شعبے میں سفارش اور اثر رسوخ سے بھرتی کیے گئے نالائق و نااہل اساتذہ کب چاہیں گے کہ ان کے بیچ کوئی صاحبِ علم استاد آکر طالب علموں میں ان کی لیاقت و قابلیت کا بھانڈا بیچ چوراہے پر پھوڑ دے۔ رفیق احمد نقش کا راستہ کسی درس گاہ سے وابستہ ہونے میں کن ’’کالی بلّیوں‘‘ نے کاٹا، اس کی روداد انھوں نے ڈاکٹر رؤف پاریکھ کو سنائی۔ ان ’’کالی بلّیوں‘‘ کے کوائف جاننے کی مجھے کوئی جستجو بھی نہیں، اس لیے کہ یہ آئے دن کے مشاہدے میں آتی اور علم اور تعلیم و تعلم کی فضا کو کس طرح اپنی تنگ دلانہ، خود غرضانہ اور مفاد پرستانہ سازشوں سے مسموم و تاریک کرتی رہتی ہیں، ان کا حال و احوال اہلِ علم سے پوشیدہ نہیں۔
یاد پڑتا ہے رفیق احمد نقش کو آخری بار میں نے پاکستان اسٹڈی سینٹر کراچی یونی ورسٹی کی لائبریری میں دیکھا تھا، جہاں انھوں نے ایم فل کی سند کے لیے داخلہ لے رکھا تھا۔ ان کے ساتھ اور بھی ایم فل کے طلبہ و طالبات تھے۔ وہ سب اس طرح بیٹھے تھے جیسے کلاس لیکچر میں جو کمی بیشی موضوع پر رہ گئی ہو اس کی تلافی اپنے لائق ساتھی رفیق احمد نقش کی صحبتِ علمی سے کرنا چاہتے ہوں۔ یہ تاثر مجھ پر یوں قائم ہوا کہ جب میں لائبریری میں داخل ہوا تو رفیق سمجھانے کے انداز میں کچھ بتارہے تھے اور ان کے کلاس فیلوز نہایت توجہ اور سنجیدگی سے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی رفیق خاموش ہوگئے، مسکرا کر سر کے اشارے سے انھوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے قریب جا کر کہا:
’’غالباً کمبائنڈ اسٹڈی ہورہی ہے!‘‘
رفیق نے صورتِ معاملہ پر پردہ ڈالنے کے لیے میرے تبصرے کو نظرانداز کیا۔ چند رسمی سی باتوں کے بعد میں رخصت ہوگیا۔ پھر رفیق سے ملنا نہ ہوا۔ مجھے نہیں معلوم کہ انھیں مذکورہ ادارے سے ایم فل کی سند ملی یا نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس ادارے میں کوئی استاد بھی ایسا نہ تھا جو رفیق کو کچھ سکھانے یا اس کے علم میں اضافے کی استعداد رکھتا ہو۔ اور یہ ایک اسی ادارے کا کیا ذکر، اب تو اکثر اعلیٰ تعلیمی اداروں کا یہی حال ہوگیا ہے۔
رفیق کا بچپن دکھوں، اذیتوں اور محرومیوں میں گزرا۔ ایک غریب محلے میں آنکھیں کھولنے اور ہوش سنبھالنے کے بعد گردو پیش کے ماحول نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ محلے کے اوباش لڑکوں کی صحبت میں بیٹھ کر جوا کھیلتے ہوئے ایک دن ماں نے دیکھ لیا۔ غصے اور جوشِ اشتعال میں آکر رفیق کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر لے کر آئیں اور چولہے میں جلتی لکڑی سے اس کی پیشانی داغ دی۔ ہونہار بیٹے کو یہ سزا راس آئی اور دوبارہ صحبتِ بد سے رجوع کی ہمت نہ ہوئی۔ لیکن ’’روایت‘‘ میں شامل اکثر مضامین سے رفیق کی طبیعت میں اصولی معاملات میں طبیعت کی خشکی اور سخت گیری کا جو سراغ ملتا ہے، نہ جانے کیوں مجھے اس سزا کا ردّعمل ہی معلوم ہوتا ہے۔ ماں اگر سمجھ دار ہوتی تو پہلے مرحلے میں سمجھانے بجھانے اور تلقین و نصیحت کا طریقہ بھی اپنا سکتی تھی۔ اگر ایسا ہوجاتا تو کیا رفیق کے چھوٹے بھائی کو وہ شکایتیں پیدا ہوتیں، ایسی دل گرفتہ شکایتیں کہ جنہیں پڑھ کر میں مغموم ہوگیا:
’’جب دیکھو، یوں لگتا ہے جیسے کسی سے لڑ کر بیٹھے ہیں یا آنے والے لمحات میں کسی سے لڑنے کی تیاری کررہے ہیں، اور لڑنے کے لیے منہ پھلا کر رکھنا گویا نہایت ضروری امر ہے۔ مجھ سے ان کے سامنے عام طور پر صحیح بھی غلط ہوجاتا ہے۔ انھیں خدا نے بلا کی خود اعتمادی عطا کی ہے۔ اس حد درجہ خود اعتمادی کی وجہ سے اکثر سامنے والا اپنا اعتماد کھو دیتا ہے۔ انھیں سامنے دیکھ کر میں تو اکثر اسی کیفیت سے دوچار ہوجاتا ہوں۔ اب نہ دست و پاہی ہلتے ہیں، نہ بولا جائے ہے۔‘‘
(بھائی جان: ازصدیق جاوید، مشمولہ روایت، علمی و کتابی سلسلہ)
چھوٹے بھائی کے رفیق کے بارے میں یہ تاثرات پڑھ کر جانے کیوں مجھے جمال احسانی پر ان کے برادرِ خرد کا تاثراتی مضمون یاد آگیا (جسے میں نے جمال پر اپنے خاکے میں نقل کیا ہے اور جو میرے شخصی خاکوں کی تازہ کتاب ’’اوراقِ ناخواندہ‘‘ میں شامل ہے۔) دونوں مضامین میں حیرت انگیز انداز اور اسلوبِ بیان کی مماثلت ہے۔ دونوں مرحومین کے چھوٹے بھائیوں نے ان کی زندگی میں ان کی موجودگی میں یہ تاثراتی مضامین لکھے اور دونوں کا شکوہ انتہائی محبت آمیز ہے۔ ان شکووں میں عجیب سا درد، نارسائی کا شدید احساس، بڑے بھائی کی مزاجی کیفیات پر شدید تشویش و اضطراب کے احساسات ملتے ہیں۔ اگر میں نفسیات کا طالب علم ہوتا، یا یہ جانتا کہ چھوٹے اور بڑے بھائی کے انسانی یا خونیں تعلق و رشتے میں کون سے رمز پوشیدہ ہوتے ہیں، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کس نظر سے دیکھتا ہے، کیا توقعات رکھتا ہے اور توقعات اور امیدیں مایوسی میں بدلتی ہیں تو چھوٹے بھائی پر کیا اور کیوں گزرتی ہے، تو شاید رفیق اور جمال کے چھوٹے بھائیوں کے احساسات کا کچھ تجزیہ کرسکتا۔ البتہ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ جلتی ہوئی لکڑی کا وہ داغ جو تاعمر رفیق کی پیشانی پر چمکتا رہا، وہ داغ پیشانی ہی پر نہیں، اس کی اذیت رفیق جیسے ہونہار و سعادت مند بیٹے کے دل سے کبھی نہ گئی۔ وہ تلخی اور خشکی بن کر اس کی اصول پسندی اور حق گوئی میں ڈھل گئی۔ ایسا تو نہیں تھا کہ رفیق کوئی بے حس اور بے درد انسان تھا، اس کے سینے میں اللہ نے نہایت دردمند دل رکھا تھا، جسے محروموں اور مفلسوں سے ایسا انس، ایسی ہمدردی تھی کہ کسی پکنک میں جب اس کے کسی دوست نے ایک غریب و نادار بچے کو پلیٹ میں سے اُٹھاکر پھل کی قاشیں پیش کیں جسے نادار مگر خوددار بچے نے لینے سے انکار کیا تو رفیق نے خفا ہوکر ٹوکا ’’تمہیں شرم نہیں آتی، اس طرح آم دیتے ہیں کسی کو۔ پلیٹ میں دے کر آؤ۔‘‘
مضمون نگار مصطفی ارباب نے واقعے کا اختتام اس تبصرے پر کیا ہے: (باقی صفحہ 43)
’’اس دوست نے ہمیشہ کی طرح ڈانٹ کھا کے ٹھیک طرح سے کام کیا‘‘۔
حالاں کہ دوست کی نیت میں کوئی خرابی نہ تھی۔ ہمدردی کے اظہار میں نادانستگی میں بھول چوک پر اتنی سختی؟ ہمیشہ کی ڈانٹ ڈپٹ؟ مگر کیوں؟ ہاں وہی جلتی ہوئی لکڑی جو رفیق کے اندر کبھی نہ بجھ سکی۔ اور ماں جس نے بیٹے کی محبت میں اصلاح کا یہ سخت گیر طریقہ اپنایا، خود بھی کوئی سنگ دل و بے رحم نہ تھی۔ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اسی ماں نے بیٹے (رفیق) کو نزدیکی قبرستان میں دفنانے کی وصیت کی اور استفسار پر وجہ یہ بتائی کہ جو فاتحہ خوانی کے لیے قبر پر آنا چاہیں انھیں آنے کی آسانی رہے۔
ہاں یہ دنیا کی زندگی ہم انسان، بہتر انسان بننے اور بنانے اور تربیت و تعمیر کے مراحل سے گزرتے، دکھ اور اذیتیں بھوگتے، کیا سے کیا بن جاتے ہیں؟ اچھے بن کر بھی پوری طرح اچھے نہیں رہتے۔ یہی ہے انسانی زندگی، یہی ہے انسانی تقدیر۔ کسی سے کیا شکوہ۔۔۔ اور کیا کسی کی شخصیت کا تجزیہ۔
رہے نام اللہ کا
ہاں مگر یہ ضرور ہے کہ رفیق احمد نقش کی پیشانی کا یہ نقش کبھی کبھی دل میں اُبھر کر اداس بھی کردیتا ہے!