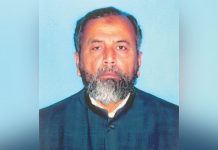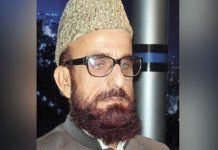حصہ اول
حالیہ صدارتی انتخابات میں ایران کے ایک صدارتی امیدوار ’’عبدالناصر ہِمّتی‘‘ صاحب تھے، ایک خبر خواں صاحبہ اسے ’’ھَمْتِیْ‘‘ پڑھ رہی تھیں، چینل میں اس طرح کی غلطیوں کی اصلاح کا کوئی نظام ہونا چاہیے۔
اَدْرِکْنِیْ : ماہرِ لسانیات جنابِ احمد حاطب صدیقی لکھتے ہیں: ’’اَدْرِکْنِیْ‘‘ کا مطلب ہے: ’’مجھے عقل، سمجھ یا فہم عطا کردے‘‘، ظاہر ہے کہ یہ کام اُس ذاتِ باری کے سوا کون کرسکتا ہے، جس نے عقل، فہم یا سمجھ تخلیق وتقسیم کی ہے، مگر بعضے لوگ مخلوق سے دعا کر بیٹھتے ہیں کہ ’’یَا فلانُ اَدْرِکْنِیْ‘‘، جانتے ہوئے کہ فلاں صاحب کی اپنی عقل وفہم بھی اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے‘‘۔
جنابِ احمد حاطب صدیقی صاحبِ علم ہیں، اُن کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھیں عربی پر بھی عبور حاصل ہے، تاہم ’’اَدْرِکْنِیْ ‘‘ کا جو مطلب انہوں نے لکھا ہے، درست نہیں ہے۔ بابِ تفاعل سے ’’تَدَارُک‘‘ کے معنی ہیں: ’’لاحق ہونا، ایک کو دوسرے کے پیچھے کرنا، آخر کا اوّل سے ملنا‘‘۔ قرآنِ کریم میں بابِ افعال سے ’’اِدراک‘‘ بھی ان معنوں میں آیا ہے: ’’لَا الشَّمْسُ یَنبَغِیْ لَہَا أَن تُدْرِکَ الْقَمَر‘‘، ترجمہ: ’’سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑ ے، (یٰس: 40)‘‘۔
’’تَدَارُکُ الْخَطائِ بِالصَّوَاب‘‘ کے معنی ہیں: ’’غلطی کی اصلاح کرنا‘‘، ’’تَدَارُکُ مَافَات‘‘ کے معنی ہیں: ’’کسی گزشتہ غلطی کی تلافی کرنا‘‘، اس کو ’’تلافیِ مافات‘‘ بھی کہتے ہیں، عربی میں ’’مَافَاتَ‘‘ کے معنی ہیں: ’’جوچیز ہاتھ سے نکل جائے‘‘، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ’’لِکَیْْلَا تَأْسَوْا عَلَی مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ وَاللّٰہُ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور‘‘، ترجمہ: ’’یہ اس لیے کہ تم اس چیز کا غم نہ کھائو جو ہاتھ سے جاتی رہی اور نہ اس چیز پر اترائو جو (اللہ) تمہیں عطا فرمادے اور اللہ کسی اِترانے والے متکبر کو پسند نہیں فرماتا، (الحدید: 23)‘‘۔ عربی میں ’’اَدْرِکْنِیْ‘‘ استغاثہ یعنی مدد طلب کرنے کے لیے آتا ہے، لغت میں ہے: ’’میری مدد کو آئو، میری مدد کرو، مجھے سنبھالو‘‘۔ بارگاہِ رسالت مآبؐ میں استغاثہ کے مشہور کلمات ہیں: ’’قَلَّتْ حِیْلَتِیْ اَنْتَ وَسِیْلَتِیْ اَدْرِکْنِیْ یَارَسُوْلَ اللّٰہ‘‘، ترجمہ: ’’میری تدبیر ناکام ہوگئی ہے، آپ ہی میرا وسیلہ ہیں، یارسول اللہ! میری دستگیری فرمائیے‘‘۔ یہاں اعتقادی مسائل زیر بحث نہیں ہیں، ہم اپنی تاویل اور بعض شرائط کے ساتھ اس کے جواز کے قائل ہیں، جبکہ بعض حضرات اس کو جائز نہیں سمجھتے۔
ایک امام بارگاہ پر لکھا ہوا تھا: ’’یَا صَاحِبَ الزَّمَانِ اَدْرِکْنِیْ‘‘، ترجمہ: ’’اے امامِ حاضر! میری مدد فرمائیے‘‘۔
مُطَّلَع: اِطّلاع کے معنی ہیں: ’’بھید بتانا، خبر دینا، اس کی جمع اطلاعات ہے، (فرہنگ عامرہ)‘‘، عربی میں ’’اِطَّلَعَ الْاَمْرَ‘‘ کے معنی ہیں: ’’جاننا، اچانک آجانا‘‘۔ ہمارے ہاں Information Ministry کو ’’وزارتِ اِطلاعات‘‘ کہتے ہیں، حالانکہ عربی میں معلومات دینے کو ’’اِعلام‘‘ اور معلومات حاصل کرنے کو ’’استعلام‘‘ کہتے ہیں۔ عربی میں’’مُطَّلَع‘‘ کے معنی ہیں: ’’آنے کی جگہ، بلندی سے جھانکنے کی جگہ‘‘، اس کے ایک معنی ہیں: ’’جس کو خبر دی جائے‘‘، کہنا تو یوں چاہیے: ’’آپ کو اِطِّلاع دی جاتی ہے‘‘ یا ’’آپ کومُطَّلَع کیاجاتا ہے، ایک فضائی میزبان اعلان کر رہی تھیں: ’’آپ کو مَطْلَع کیا جاتا ہے‘‘، حالانکہ ’’مَطْلَع‘‘ کے معنی ہیں: ’’ستارے کے طلوع ہونے کی جگہ‘‘، سیڑھی کو بھی ’’مَطْلَع‘‘کہتے ہیں، یعنی چڑھنے کی جگہ، غزل کے پہلے شعر کو مَطلع اور آخری شعر کو مَقطَع کہتے ہیں۔
دعائے سفر: ہوائی جہاز میں ’’دعائے سفر’سُبْحَانَ الَّذِیْ سَخَّرَلَنَاھٰذَا وَمَا کُنَّا لَہٗ مُقْرِنِیْنَ oوَاِنَّا اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ‘‘ پڑھی جاتی ہے اور اس کے آخر میں فضائی میزبان ’’صَدَقَ اللّٰہُ الْعَظِیْم‘‘ پڑھتا ہے، یہ کلمات معنوی اعتبار سے تو درست ہیں اور قرآنِ کریم کی تلاوت کے اختتام پر ان کا پڑھنا معمول ہے، اگرچہ یہ کلمات حدیث سے ثابت نہیں ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے درست ہیں۔ مگر جب دعائے سفر پڑھی جائے تو آخر میں ’’صَدَقَ اللّٰہُ الْعَظِیْم‘‘ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اُس وقت ہم ان کلمات کو دعا کی نیت سے پڑھتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں اور ’’صَدَقَ اللّٰہُ الْعَظِیْم‘‘ تلاوت کے بعد پڑھا جانا متعارف ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم دعا کی نیت سے ’’ُرَبَّنَا آتِنَا فِیْ الدُّنْیَا حَسَنَۃً وَفِیْ الآخِرَۃِ حَسَنَۃً وَقِنَا عَذَابَ النَّار‘‘ پڑھتے ہیں تو آخر میں ’’صَدَقَ اللّٰہُ الْعَظِیْم‘‘ نہیں کہتے۔ تلاوتِ قرآن کے بعد ’’صَدَقَ اللّٰہُ الْعَظِیْم‘‘ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ان کلمات پر اللہ کا کلام ختم ہوا، جیسے انگریزی میں ہم کسی کی بات یا حوالہ نقل کرکے کہتے ہیں: ’’ Quote Unquote‘‘۔
(جاری ہے)
اَمْتُل فاطمہ: اس نام کی کسی خاتون کے ایصالِ ثواب کی تقریب کا ایک قومی اخبار میں اشتہار تھا، اس کا صحیح رسم الخط ’’اَمَۃُ الْفَاطِمۃ‘‘ ہے، اس کے معنی ہیں: ’’لختِ جگرِ رسولؐ سیدہ فاطمۃ الزہراؓ کی باندی‘‘۔ فرطِ عقیدت کی وجہ سے اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں، جیسے: ’’غلام رسول، غلام مصطفی، غلام عمر، غلام علی، غلام حسن، غلام حسین وغیرہ ‘‘، ’’اَمَۃٌ‘‘ باندی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ’’اِمَاء‘‘ ہے، اس کو ملاکر ’’اَمْتُل فَاطِمہ‘‘ لکھنا غلط ہے۔
غیر مُرِی: قومی اسمبلی کی ایک خاتون رکن ’’غیر مُرِی‘‘ بول رہی تھیں، دراصل یہ لفظ عربی میں ’’مَرْئِیٌّ‘‘ ہے، اس کے معنی ہیں: ’’جو دکھائی دے‘‘ یا ’’جو نظر آئے‘‘، اردو میں تخفیف کے ساتھ اسے ’’مَرئی‘‘ لکھتے اور بولتے ہیں، پس ’’غیر مرئی‘‘ کے معنی ہیں: ’’جو نظر نہ آئے (Unseen)‘‘، آج کل سیاست میں اسے ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تاہم ’’مُرِیْ‘‘ تلفظ غلط ہے۔
شرقِ اَوسَط: مڈل ایسٹ کے لیے عالمِ عرب میں ’’اَلشَّرْقُ الْاَوْسَط‘‘ جبکہ ہمارے ہاں ’’مشرقِ وُسطیٰ‘‘ بولا جاتا ہے، ’’وُسطیٰ‘‘ مؤنث کا صیغہ ہے۔ عربی لفظ مشرق جہت کے معنی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، اردو لغت میں اسے مذکر بھی لکھا گیا ہے، الغرض معنوی اعتبار سے دونوں کا استعمال درست ہے، لیکن شرقِ اوسَط بہتر ہے۔
گالی گلوچ: گالی کے معنی ہیں: ’’دشنام، بدزبانی، فحش بات‘‘۔ گالی دینا یا گالی سنانا کے معنی ہیں: ’’بدزبانی کرنا، منہ سے بری بات نکالنا‘‘، گالی کھانا کے معنی ہیں: دشنام سننا، بدزبانی کو برداشت کرنا، غالب نے کہا ہے:
کتنے شیریں ہیں تیرے لب، کہ رقیب
گالیاں کھا کے، بے مزا نہ ہوا
اسی سے ’’گالی گلوچ‘‘ آتا ہے، اس کے معنی ہیں: ’’ایک دوسرے کو گالیاں دینا، بدزبانی کرنا وغیرہ‘‘۔ آج کل ’’گالم گلوچ‘‘ کے الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ یہ لغت میں ہیں، لیکن فصیح نہیں ہیں۔
انشاء اللہ: ایک انتہائی تجربہ کار تجزیہ کار، ادیب اور صحافی نے اپنے کالم کا عنوان ’’انشاء اللہ‘‘ رکھا، وہ عربی پر بھی دست رس رکھتے ہیں اور کبھی کبھی حوالے بھی دیتے ہیں، لیکن ہر انسان سے کہیں نہ کہیں سہو اور خطا سرزد ہوجاتی ہے یا عدمِ توجہ کی بنا پر تسامح ہوجاتا ہے۔
’’اگر اللہ نے چاہا‘‘ کے معنی میں لکھنا ہو تو ’’اِنْ شَآئَ اللّٰہ‘‘ لکھنا چاہیے، اس میں ’’اِنْ ‘‘حرفِ شرط ہے اور ’’شَآئَ‘‘ بمعنی ’’چاہا ‘‘ فعلِ ماضی ہے، ’’شَائَ یَشَائُ‘‘ کا مصدر ’’شَیْئًا اور مَشِیْئَۃً‘‘ ہے، اس کے حروفِ اصلی ’’ش ی ء‘‘ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ’’وَلَا تَقُولَنَّ لِشَیْْئٍ إِنِّیْ فَاعِلٌ ذَلِکَ غَداًoإِلَّا أَن یَّشَآء َ اللّٰہُ‘‘، ترجمہ: ’’اور آپ کسی کام کے متعلق یہ ہرگز نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، (الکہف: 23-24)‘‘، یعنی یہ کہنا چاہیے: ’’ان شاء اللہ! میں کل یہ کام کروں گا‘‘ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ’’وَمَا تَشَآؤُونَ إِلَّا أَن یَّشَآء َ اللّٰہُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ‘‘، ترجمہ: ’’اور تم نہیں چاہتے مگر جو اللہ رب العالمین چاہے، (التکویر: 29)‘‘، یعنی جب بندے کی چاہت اللہ کی چاہت کے مطابق ہوجائے تو وہ اللہ کے فضل سے پوری ہوکر رہتی ہے۔
اِنشاء: اِنشاء کے حروف اصلی ’’ن ش ء‘‘ ہیں، اس کی اصل ’’نَشْاۃ‘‘ ہے،’’نَشأَۃُ الشَّیْء‘‘ کے معنی ہیں: نوپید ہونا، زندہ ہونا۔ ’’اَنْشَأَ اللّٰہُ الشَّیْئَ‘‘ کے معنی ہیں: اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو پیدا کرنا، اس کا مصدر ’’اِنْشَاء‘‘ بمعنی پیدا کرنا ہے۔ عربی میں مصدر کبھی فاعلی معنی میں ہوتا ہے اور کبھی مفعولی معنی میں، یہاں مفعولی معنی میں ہے، پس ’’اِنْشَآئُ اللّٰہ‘‘ کے معنی ہیں :’’اللہ کی مخلوق‘‘، اِنشائُ اللّٰہ خان اِنشاؔ کے نام سے معروف ادیب اور شاعر گزرے ہیں۔ افضل یہی ہے کہ ہم ’’اگر اللہ نے چاہا‘‘ کے معنی میں لکھنا چاہیں تو قرآنِ کریم کے اتباع میں ’’اِنْ شَآئَ اللّٰہ‘‘ ہی لکھیں، تاہم اگر یہی معنی ذہن میں رکھتے ہوئے ملا کر ’’اِنشائَ اللہ‘‘ لکھ دیا تو اس پر کوئی شرعی حکم تو نہیں لگے گا، لیکن بہتر قرآن کے رسم الخط کا اتباع ہے۔
اِبہام: الف کی زیر کے ساتھ اِبہام کے معنی ہیں: ’’کسی بات کا غیر واضح ہونا، کھول کر بیان نہ کرنا‘‘، ایک صاحب الف کے زبر کے ساتھ ’’اَبہام‘‘ بول رہے تھے، جو درست نہیں ہے، اِبہام انگوٹھے کو بھی کہتے ہیں۔
امنِ عامّہ: ’’عَامَّۃُ النَّاس‘‘ کے معنی ہیں: ’’عام لوگ‘‘ اور ’’امنِ عامّہ‘‘ کے معنی ہیں: ’’عام لوگوں کے لیے امن وامان اور بے خوفی کا ماحول‘‘۔ ایک صاحب ’’اَمنُ وعامّہ‘‘ بول رہے تھے، جو غلط ہے۔
سرِ تسلیم خم: ’’تسلیم‘‘ کے معنی ’’سپردگی‘‘ کے ہیں، اسے انگریزی میں ’’Submission‘‘ کہتے ہیں، ’’ سرِ تسلیم خم کرنے‘‘ کے معنی ہیں: ’’فرمانبرداری کرنا، حکم ماننا‘‘، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ’’إِذْ قَالَ لَہُ رَبُّہُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِیْنَ‘‘، ترجمہ: ’’جب اُن سے اُن کے رب نے کہا: میری اطاعت پر (برقرار) رہو، انہوں نے کہا: میں تمام جہانوں کے رب کی اطاعت پر قائم ہوں، (البقرہ:131)‘‘۔ حالیہ دنوں میں بعض حضرات سے ’’سرِ خمِ تسلیم‘‘ اور بعض سے ’’سرِ تسلیمِ خم‘‘ سننے میں آیا ہے، یہ دونوں غلط ہیں، فارسی میں زیر کے ساتھ اضافت ہوتی ہے، تو سرِ تسلیم مرکبِ اضافی ہے اور اس کی آگے ’’خم‘‘ کی طرف اضافت نہیں ہے۔ ’’خَم‘‘ کے معنی ہیں: ’’ٹیڑھاپن، ٹیڑھا‘‘۔ خ کی پیش کے ساتھ ’’خُم‘‘ کے معنی ہیں: ’’مٹکا، گھڑا، بڑی ہانڈی‘‘، شاعر نے کہا ہے:
جس بزم میں ساغَر ہو، نہ صہبا ہو، نہ خُم ہو
رِندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو
(جاری ہے)
خوش آمدید! اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں
اپنا پاسورڈ ريکور کريں
Daily Jasarat News is proudly powered by WordPress